کیمبرج یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے ایک بالکل نئی ٹیکنالوجی کے تحت کپڑے کو ڈسپلے اسکرین اور ٹچ سینسر میں تبدیل کردیا۔
برطانوی میڈیا کے مطابق اس انوکھے کام میں اسمارٹ ٹیکسٹائل میں سینسر بُنے گئے ہیں اور ان میں فائبر ایل ای ڈی لگائی گئی ہیں جس کے ذریعے پورے کپڑے کو ایک طرح کے ٹچ ڈسپلے میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 46 ٹیکسٹائل ڈسپلے تیار کیا گیا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ کپڑا سازی کے روایتی طریقے سے بھی اسمارٹ کپڑے کو بنایا جاسکتا ہے۔
اگرچہ پہلے بھی کئی طرح کی اسمارٹ پوشاک بنائی گئی ہیں۔ بعض کپڑے دھوپ اور حرکت سے توانائی کشید کرتے ہیں۔ کچھ میں چھونے کا احساس بھی شامل کیا گیا ہے۔ بعض لباس گرمی میں سرد اور سردی میں گرم ہوسکتےہیں لیکن یہ پہلا کپڑا ہے جس میں کئی طرح کے خواص موجود ہیں۔
اس میں فائبر پر مشتمل ایل ای ڈی روشنیاں لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ دیگر پرزہ جات بھی فائبر سے ہی کاڑھے گئے ہیں جن میں ٹچ اور درجہ حرارت نوٹ کرنے والے سینسر کے ساتھ ساتھ اینٹینا اور بایو سینسر بھی شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ توانائی محفوظ کرنے کا نظام بھی ریشے کی صورت میں ڈھالا گیا ہے۔
تکمیل کے بعد اب کپڑے پر مختلف تصاویر اور رنگ نمودار ہوتے ہیں۔ اس میں ٹچ اسکرین کی سہولت بھی موجود ہے اور یہ درجہ حرارت بدلنے اور لوگوں کے چلنے سے بجلی بناتا رہتا ہے۔
فائبر میں ہونے کے وجہ سے انہیں من پسند کپڑے یا سویٹر وغیرہ میں ڈھالا جاسکتا ہے اور لچک دار ہونے کی بنا پر یہ کھنچنے سے خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے ڈسپلے اسکرین والا کپڑا طویل عرصے تک کارآمد رہتا ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق یہ انٹرنیٹ آف تھنگس کی بہترین مثال ہے اور ماہرین کے مطابق اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔
https://www.express.pk/story/2283857/508/
امریکی سائنس دانوں نے ایک ایسی ذہین گھڑی ایجاد کرلی ہے جو پسینے میں شامل ’کورٹیسول‘ کی پیمائش کرتے ہوئے اعصابی تناؤ معلوم کرتی ہے۔
یہ گھڑی خاص طور پر ایسے افراد کےلیے بنائی گئی جنہیں ڈپریشن (اضمحلال) اور اینگژائٹی (تشویش) جیسے نفسیاتی مسائل کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
’کورٹیسول‘ کہلانے والے ایک ہارمون کو انسانی جسم میں تناؤ کا پیمانہ بھی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اعصابی تناؤ بڑھنے کے ساتھ ساتھ خون اور پسینے میں اس ہارمون کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں، زیادہ اعصابی تناؤ کا نتیجہ ڈپریشن، اینگژائٹی اور اسی نوعیت کے دوسرے نفسیاتی مسائل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جسم میں کورٹیسول کی مقدار پر مسلسل نظر رکھی جائے تو اعصابی تناؤ کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور اینگژائٹی کے خطرات سے بھی باخبر رہا جاسکتا ہے۔
یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس (یو سی ایل اے) کے ماہرین کی ٹیم نے پروفیسر اینی اینڈریوز اور ایسوسی ایٹ پروفیسر سیم امامی نژاد کی قیادت میں یہ ذہین گھڑی (اسمارٹ واچ) تیار کی ہے۔
اس گھڑی کا پچھلا حصہ بہت معمولی مقدار میں بھی پسینہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
پسینہ جذب ہوتے ہی ایک خردبینی نظام (مائیکرو فلوئیڈک اسٹرکچر) میں پہنچایا جاتا ہے جہاں ڈی این اے کے مخصوص ٹکڑوں کی مدد سے پسینے میں کورٹیسول کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔
اس ذہین گھڑی کو جیسے ہی جسم میں معمول سے زیادہ کورٹیسول کا پتا چلتا ہے، یہ فوراً اپنے پہننے والے کو خبردار کردیتی ہے تاکہ وہ اعصابی تناؤ پر قابو پانے کےلیے ضروری اقدامات کرلے۔
چونکہ ہر انسان کےلیے ’نارمل کورٹیسول‘ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے لہذا پہلے اس گھڑی کی سیٹنگ اسے پہننے والے کے حساب سے کی جاتی ہے۔
فی الحال اس ذہین گھڑی کا پروٹوٹائپ تیار ہوچکا ہے جسے ابتدائی طور پر آزمایا بھی جاچکا ہے۔
البتہ اس کے تجارتی پیمانے تک پہنچنے اور فروخت کےلیے دستیاب ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔
نوٹ: اس ایجاد کی تفصیل آن لائن ریسرچ جرنل ’’سائنس ایڈوانسز‘‘ کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔
https://www.express.pk/story/2283595/9812/
خلا میں مقناطیسی طوفان، ایلون مسک کی سپیس ایکس کے درجنوں انٹرنیٹ سیٹلائٹ برباد، لیکن زمین پر اس کا کیا اثر پڑا؟
Feb 10, 2022 | 18:19:PM

سورس: Pixabay.com (creative commons license)
نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) خوفناک شمسی طوفان نے خلاءمیں موجود امریکی کمپنی سپیس ایکس کی 40 انٹرنیٹ سیٹلائٹس کو تباہ کر دیا ہے، جس سے زمین پر کمپنی کی انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئی ہے۔ نجی ٹی وی چینل 24نیوز کے مطابق دنیا کے امیر ترین آدمی ایلون مسک کی کمپنی سپیس ایکس نے 49سیٹلائٹس حال ہی میں مدار میں بھیجی تھیں۔ یہ سیٹلائٹس کینیڈی سپیس سنٹر، فلوریڈا سے لانچ کی گئی تھیں۔ یہ سپیس ایکس کی ذیلی انٹرنیٹ کمپنی سٹارلنک نیٹ ورک کی تھیں۔
ان 49میں سے 40سیٹلائٹس خوفناک ارضی مقناطیسی طوفان کی زد میں آ کر اپنے مدار سے نکل گئیں۔ کمپنی کی طرف سے جاری ایک بیان میں 40سیٹلائٹس کے تباہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مدار سے نکلنے والی ان سیٹلائٹس سے زمین پر کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ زمین کی طرف گرتے ہوئے فضاءمیں ہی رگڑ کی قوت کے سبب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ کمپنی کے مطابق یہ سیٹلائٹس پہلے مرحلے میں زمین سے 210کلومیٹر کی بلندی پر مدار میں چھوڑی گئی تھیں جہاں یہ شمسی طوفان کی زد میں آ گئیں۔
واضح رہے کہ کمپنی سیٹلائٹس کو پہلے اس جگہ مدار میں چھوڑ کر ان کی سیفٹی کے حوالے سے حتمی طور پر انہیں چیک کرتی ہے اور پھر تسلی ہونے پر انہیں یہاں سے آگے خلاءمیں مزید بلندی میں پہنچا دیا جاتا ہے۔سٹارلنک اب تک 2ہزار سے زائد سیٹلائٹس خلاءمیں بھیج چکی ہے جن کی بدولت اس کی انٹرنیٹ سروس لگ بھگ پوری دنیا میں میسر ہے۔برطانوی سپیس ایجنسی کے مطابق اس وقت خلاءمیں سٹارلنک کی ان 2ہزار سیٹلائٹس سمیت کل لگ بھگ 4ہزار ایکٹو سیٹلائٹس موجود ہیں جو زمین سے 1200میل کی بلندی پر مدار میں گردش کر رہی ہیں۔
https://dailypakistan.com.pk/10-Feb-2022/1401559?fbclid=IwAR0fy4r7LLikDV9o2th1KlcDmjVlLeTW3iJv2UraXTUNaL837atPosoWjgE
سائنسدانوں نے گھروں کو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد رکھنے والی اسمارٹ کھڑکی تیار کرلی ہے۔
آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کھڑکیوں کے شیشے کے لیے ایک اسمارٹ کوٹنگ تیار کی ہے جو گرمی میں حرارت کو منعکس کرتی ہے اور سردیوں میں حرارت کو اندر آنے دیتی ہے جس سے دونوں موسموں کی سختیاں کم ہوسکتی ہیں۔
کھڑکی کے شیشے پر لگائی گئی پرت سے کمرہ میں حدت کی مقدار کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
کھڑکی کے شیشے پر چالکوگینائڈ مٹیریئل کی پرت لگائی گئی ہے جو حرارت کے تحت اپنی کیفیت بدلتا ہے۔ سردیوں میں یہ دھوپ سے انفراریڈ شعاعیں جذب کرتا ہے اور اس کی گرمی کمرے میں بکھیرتا ہے۔ سلیکن سردی میں یہ الٹا عمل کرتا ہے اور کمرے کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح بدلتے موسم کے تحت یہ کھڑکی کام کرتی ہے اورگرمیوں میں کمرے کی حدت تیسرے حصے تک کم کردیتی ہے۔
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں اس میں ایک شفاف ہیٹر بھی لگایا ہے جو مختلف ڈگریوں پر گرمی اور سردی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ شیشہ 30 سے 70 فیصد تک حرارت لوٹا سکتا ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی عمارتوں کو گرم اور سرد رکھنے کے لیے بجلی کا بل غیرمعمولی طور پر کم کیا جاسکتا ہے
https://www.express.pk/story/2282926/508/
کراچی کے نوجوان انجینئر نے آٹزم کا شکار بچوں کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور ان سے بات چیت کے ذریعے تنہائی دور کرنے کے لیے روبوٹ تیار کرلیا۔
روبوٹ کو حال ہی میں قومی سطح پر ”نیشنل آئیڈیاز بینک“ کے تحت ہونے والے تخلیقی آئیڈیاز کے مقابلوں میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کا بہترین تخلیقی آئیڈیا قرار دیا گیا اور صدر مملکت عارف علوی نے تخلیقی آئیڈیا متعارف کرانے والے نوجوان انجینئر محمد علی عباس کو ہیلتھ کٹیگری کے آئیڈیاز کے مقابلے میں اول پوزیشن کی سند کے ساتھ 75ہزار روپے کے نقد انعام سے بھی نوازاہے۔
اس حوالے سے عثمان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے فارغ التحصیل محمد علی عباس نے بتایا کہ ورلڈ بینک کے اندازے کے مطابق پاکستان میں 10لاکھ بچے آٹزم کا شکار ہیں اور ایسے بچوں کے ذہنی اورجسمانی مسائل کے حل کے لیے تربیت یافتہ ماہرین اور عملے کی کمی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ روبوٹ کی خصوصیات کو مزید بہتر بنایا جارہا ہے تاکہ پاکستان میں آٹزم کے شکار بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ عالمی سطح پر بھی اسپیشل بچوں کے لیے فراہم کیا جاسکے جبکہ آئندہ 4 ماہ میں مکمل پراڈکٹ مارکیٹ میں پیش کی جائیگی۔
محمد علی عباس نے بتایا کہ ابتدا میں آٹزم کا شکار بچوں کے انسٹی ٹیوٹس کو ایسے روبوٹ فراہم کیے جائیں گے، روبوٹ میں کیمرا نصب ہے اور ٹچ سینسرز کے ساتھ الٹراسونک سینسرز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ آٹزم کا شکار بچوں میں چھونے سے متعلق مسائل کو دور کیا جاسکے۔
ان کا کہنا تھا کہ روبوٹ مشین لرننگ اور الگورتھم پر کام کرتا ہے ایک موبائل ایپلی کیشن بچوں کا ڈیٹا لے کر روبوٹ سے کنیکٹ ہوگی، روبوٹ آٹزم کا شکار بچوں کے جذبات کو شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2282868/1/
سوئس فیڈرل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی لوزین سے وابستہ سائنسدانوں نے برسوں کی محنت کے بعد مکمل طور پر مفلوج تین افراد کو چلنے کے قابل بنایا ہے۔ یہ تینوں افراد ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی چوٹ کےبعد نچلے دھڑ کو چلانے والے برقی سگنل کھوچکے تھے۔
اعصابی ماہر ڈاکٹر گریگوئر کورٹائن اور سرجن جیکولین بلوخ پہلے 2018 میں اس کا انکشاف کیا تھا۔ لیکن اب انہوں نے ایک بہتر نظام بنایا ہے جو مصنوعی ذہانت سافٹ کی بدولت حرام مغز میں برقی سرگرمی دیتے ہیں جس کے بعد ان ک اعصابی سگنل فائر ہونے لگے۔ اس طرح تھراپی کے چند گھنٹوں بعد ہی اعصابی نظام حرکی یا موٹر نظام کو چلانے لگا اور وہ پاؤں اٹھانے کے قابل ہوگئے۔
اس کے لیے مریضوں کے حرام مغز کے اس مقام پر برقی پیوند لگائے گئے تھے جو نچلے دھڑ اور ٹانگوں کو برقی سگنل دے کر انہیں حرکت پہنچارہے تھے۔ اس سے پورا نظام سرگرم ہوا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ کمر میں لگائے گئے برقی پیوند کی سرگرمی کو ٹیبلٹ ایپ کے ذریعے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ ان ہدایات کی روشنی میں وہ برقی امپلانٹ کام کرتا ہے۔
اس سے قبل حرام مغز میں برقی رو پہنچاکر درد کا علاج کیا جاتا رہا تھا لیکن اب مکمل طور پر مفلوج تین افراد کو چلنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ یہ پیوند مسلسل برقی سگنل خارج کرتا رہتا ہے اور مریض کے نچلے دھڑ کو تقویت ملتی ہے۔
اس کے لیے ایک نئی طرز کا برقیرہ یا الیکٹروڈ ایجاد کئے گئے جو رانوں اور ٹانگوں کے تمام اعصاب پر اثر کرتے ہیں۔ پھر ہر مریض میں ضرورت کے تحت برقی سرگرمی پہنچائی گئی۔
تینوں مرد مریضوں می عمر 29 سے 41 برس ہے جن کا نچلا دھڑ اور ٹانگیں بے حس ہوچکی تھیں۔ بہت جلد وہ تیراکی اور سائیکل چلانے کے بھی قابل ہوجائیں گے۔
https://www.express.pk/story/2282486/9812/
دردِ سر کی ایک تکلیف دہ صورت نیوریلگیفورم ہے جو بہت دیر تک برقرار رہتی ہے۔ اب ٹیفلون کا ایک باریک ٹکڑا پیوند کی صورت میں لگانے سے اس مرض سے جان چھڑائی جاسکتی ہے۔
اس ٹیکنالوجی کی افادیت کے تحت اسے ایک انقلابی عمل قرار دیا جارہا ہے۔ اگرچہ اس کے سائنسی نتائج ابھی شائع نہیں ہوئے لیکن تحقیقی مقالوں کی پری پرنٹس ویب سائٹ کے تحت اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس میں ٹیفلون کا ایک پیوند دماغ می لگانے سے درد کے سگنل بلاک ہوجاتے ہیں اور مریض کو سکون مل جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس عمل سے گزرنے والے 60 فیصد مرض اب خوفناک دردِ سر سے دائمی نجات حاصل کرچکے ہیں۔ اس قسم کے دردِ سر کا پورا نام ’شارٹ لاسٹنگ یونی لیٹرل نیولیگیفورم ہیڈ ایک ود کونجکٹیول انجیکشن اینڈ ٹیئرز‘ یا ایس یو این سی ٹی ہے ۔
اگرچہ یہ ایک نایاب مرض ہے لیکن پوری دنیا میں اس کیفیت کے مریض موجود ہے۔ مردوں میں یہ بیماری 50 برس کے بعد حملہ آور ہوسکتی ہے جس میں چہرے ، جبڑے اور مسوڑھوں میں شدید درد ہوتا ہے گویا کہ کوئی خنجر گھونپ رہا ہے۔ اس کی شدت سے آنکھوں اور ناک سے پانی بہنا شروع ہوجاتا ہے۔
اگرچہ اس مرض کو مکمل طور پر سمجھا نہیں گیا ہے لیکن ایس یو این سی ٹی میں دماغ کا ایک اعصابی رگ شدید متاثر ہوتی ہے جسے ٹرائی جیمینل نرو کہا جاتا ہے۔
اس مرض میں بعض دفعہ چہرے پر بجلی کے شدید جھٹکے بھی محسوس ہوتے ہیں اور مسلسل کیفیت انسان کو روزگار سے بھی محروم کرسکتی ہے۔
برطانیہ کے گائے اینڈ سینٹ تھامس ہسپتال میں ڈاکٹر جورجیو لیمبرو کی نگرانی میں فی الحال 50 مریضوں کو ٹیفلون کا پیوند لگایا گیا ہے۔ اس میں کان کے پیچھے سے کھوپڑی کا ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر دماغ کی جڑ میں ٹرائجیمینل اعصابی تار اور اس کے پاس موجود خون کی شریان کو الگ کردیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کی بیچ پولی ٹیٹرافلوروایتھائلین یعنی ٹیفلون کا ایک معمولی سا ٹکڑا رکھ کر دونوں کو الگ کردیا جاتا ہے۔
اس طرح دو تہائی مریضوں نے بتایا کہ آپریشن کے بعد ان کا شدید درد غائب ہوگیا اور اب تک وہ درد سے مکمل طور پر آزاد ہیں۔
https://www.express.pk/story/2282093/9812/
https://www.express.com.pk/epaper/PoPupwindow.aspx?newsID=1109015820&Issue=NP_PEW&Date=20220209
گھریلو بجلی یعنی کرنٹ کی دریافت کو اگر تاریخ ساز دریافت کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ جدید دور کا تقریباً کُل انحصار اسی بجلی پر ہے لیکن اگر پوچھا جائے کہ اس کا دریافت کنندہ کون تھا تو اکثریت بنجیمن فرینکلن کا نام لے گی جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔
بنجیمن فرینکلن کا چابی کو پتنگ کی ڈور سے جوڑ کر بجلی کے کرنٹ کا تجربہ کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ سائنسدان 1752 میں ہی اس کے وجود سے واقف تھے۔ اور حیرت انگیز طور پر صرف سائنسدان ہی نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے سے انسان کرنٹ کے وجود سے واقف رہا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں اُسے استعمال بھی کرتا رہا ہے۔
فرینکلن جو تجربے سے بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ بجلی یا کرنٹ کا وجود ہے بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آسمانی بجلی بھی کرنٹ کی کوئی قسم ہے اور اسی کا اُس نے نظریہ بھی پیش کیا تھا۔
ہزاروں سال پہلے کی بات اگر کی جائے تو سب سے پہلے یونان نے بجلی کے وجود کا نظریہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جیواشم درختوں کی گوند یعنی عنبروں کو کسی جاندار کی کھال سے رگڑنے سے سوکھی گھاس چپکنے لگتی ہے۔ اسے static electricity کہا جاتا ہے۔
اسی طرح قدیم مصر کے باشندے برقی لہریں پیدا کرنے والی دریائے نیل کی مچھلی کیٹ فِش سے واقف تھے اور وہ اس مچھلی کو سردرد یا عرق النساء کے درد میں علاج کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس تھیراپی کو ichthyoelectroanalgesia کہا جاتا ہے اور یہ تھیراپی 1600 عیسوی تک جاری رہی۔
ایک اور عجیب بات یہ کہ ممکن ہے اُرُتی پتنگ سے چابی جوڑنے کا تجربہ فرینکلن نے بذات خود کیا ہی نہ ہو۔ فرینکلن نے Pennsylvania Gazette اخبار میں محض اس تجربے کی کامیابی اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں لکھا تھا، اُس نے یہ کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ یہ تجربہ اس نے خود کیا۔
15 سال بعد جوزیف پریسٹلی نامی سائنسدان نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اس تجربے کا ماسٹر مائنڈ بنجیمن فرینکلن کو قرار دے دیا۔
https://www.express.pk/story/2281979/509/
اس سمندری جانور کی لمبائی 8 سے 10 سینٹی میٹر لمبی ہوسکتی ہے لیکن اس میں کئی اقسام کے زہرپائے جاتےہیں جو کئی بیماریوں کے لیے شفا ثابت ہوسکتے ہیں۔
کوئنز لینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی ڈاکٹر لورین ایش وُڈ اور ان کے ساتھیوں نے کئی اقسام کے سی اینیمن کا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک مشہور سی اینیمن میں 84 طرح کے زہرپائے جاتے ہیں۔ ماہرین نے دیکھا ہے کہ جانور کی آنتوں، اس کے ابھار اور جسم کے دیگر حصوں میں طرح طرح کے زہر موجود ہیں۔
ڈاکٹر لورین کے مطابق اس کے ہر زہر کا کام بھی الگ ہے۔ کسی زہر سے یہ شکار کو بے بس کرتا ہے، دوسرے زہر سے یہ اپنا دفاع کرتا ہے اور تیسرے زہر سے نظامِ ہاضمہ کا کام لیتا ہے۔ مختلف اقسام کے خلیات سے یہ زہر خارج ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں نے ان زہروں کے معالجاتی پہلوؤں پر غور شروع کیا ہے۔
اس زہریلے سی اینیمن کا نام Telmatactis stephensoni ہے جو آسٹریلیا کے سمندروں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اب تک ایک ہی جانور میں زہر کی اتنی بڑی مقدار کبھی نہیں دیکھی گئی ہے۔ اس کا زہر نکال کر ہنگری میں موجود ایک جدید لیبارٹری میں بھجوایا گیا ہے۔
سب سے پہلے اس میں ایک نئے زہر یو ٹی ایس ٹی ایکس ون کا انکشاف ہوا ہے جس سے خود سائنس نا واقف تھی۔ یہ زہر چکنائی کو چھوٹے سالمات میں توڑتا ہے۔ دوسرے زہر سے درد دور کرنے والی ادویہ بنائی جاسکتی ہیں۔
اس کے علاوہ ایک اور زہر ملا ہے جو نیوروٹاکسن ہے اور ایک بلاکر کے طور پر کام کرتے ہوئے کمر کے شدید درد کا علاج بن سکتا ہے۔
اس طرح یہ چھوٹا سا جانور کئی طرح کا ادویاتی دواخانہ ثابت ہوسکتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2282058/9812/
امریکی اسٹارٹ اپ کمپنی ’ڈی نووو‘ نے کھال، خون اور چکنائی کے خلیوں سے اصلی بال اُگانے والی جدید ’ڈائریکٹ ری پروگرامنگ ٹیکنالوجی‘ وضع کرلی ہے جس سے گنج پن کا علاج بھی ’بہت جلد‘ شروع کردیا جائے گا۔
اس ٹیکنالوجی کے تحت کسی شخص کی کھال، خون یا چکنائی کے خلیے لے کر انہیں کچھ خاص مادّوں (پروپرائٹری ری پروگرامنگ فیکٹرز) کے ذریعے ’ری پروگرام‘ کیا جاتا ہے اور وہ بال اُگانے والے خلیوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔
پھر ان خلیوں ساق کو ’بیجوں کی طرح‘ اسی شخص کی کھوپڑی میں پیوند کردیا جاتا ہے کہ جس سے کھال، خون یا چکنائی کے خلیے حاصل کیے گئے تھے۔
ڈی نووو کمپنی کا دعوی ہے کہ اس طرح ایک سے تین ماہ میں سر پر اُگنے والے بال نمایاں ہونے لگیں گے اور یوں گنج پن بتدریج ختم ہوجائے گا۔
اس حوالے سے ایک پریس ریلیز میں ’ڈی نووو‘ نے بتایا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی نے اہم سنگِ میل عبور کرلیا ہے جس میں ایک گنجے چوہے کے جسم پر صرف تین ہفتے میں نئے بال کامیابی سے اگا لیے گئے جو اگلے سات ماہ تک اگتے رہے۔
گنجے چوہوں کی یہ نسل جینیاتی انجینئرنگ سے تیار کی گئی تھی۔
اگرچہ نئے قدرتی بال اگانے کی مختلف ٹیکنالوجیز پہلے ہی سے موجود ہیں لیکن وہ سب خاصی پیچیدہ ہیں جن کے تحت خلیوں کی ’ری پروگرامنگ‘ کرکے انہیں بال اُگانے والے خلیاتِ ساق میں تبدیل کرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے جبکہ متعدد بار ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔
’ڈی نووو‘ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی کھال، خون یا چکنائی کے خلیوں کو براہِ راست بال اُگانے والے نئے خلیات میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت تیزرفتار ہے جس کا راز ان کے اپنے تیار کردہ ’پروپرائٹری ری جنریشن فیکٹرز‘ میں پوشیدہ ہے۔
یہ ’فیکٹرز‘ کیا ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں؟ اس بارے میں ’ڈی نووو‘ نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے البتہ اتنا ضرور بتایا ہے کہ ان منفرد مادّوں کا پیٹنٹ حاصل کرنے کےلیے درخواست دی جاچکی ہے۔
اپنی تمام مبینہ خوبیوں کے باوجود، اصلی بال اُگانے والی اس نئی ٹیکنالوجی کو ادویہ اور علاج معالجے کے طریقوں کی منظوری دینے والے مرکزی امریکی ادارے ’فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن‘ (ایف ڈی اے) سے اجازت درکار ہوگی، جس میں خاصا وقت بھی لگ سکتا ہے۔
’ڈی نووو‘ نے وائی کمبی نیٹر، فیلیسس وینچرز اور دوسرے اداروں سے 27 لاکھ ڈالر کی بنیادی فنڈنگ بھی حاصل کرلی ہے تاکہ اس کام کو تیزی سے آگے بڑھایا جاسکے۔
البتہ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ ’ڈائریکٹ ری پروگرامنگ‘ ٹیکنالوجی انسانوں کا گنجا پن دور کرنے میں بھی اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں کہ جتنی یہ چوہوں میں کامیاب رہی ہے۔
https://www.express.pk/story/2281926/9812/
ہمارے معدے اور آنتوں میں بعض ایسے خردنامیوں یعنی مائیکروبس کا انکشاف ہوا ہے جو کسی نہ کسی وقت بدن میں چربی بڑھا کر ہمیں موٹا کردیتے ہیں۔ اب سائنسداں اس پورے سالماتی عمل اور طریقہ واردات کو سمجھنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
ایموری یونیوسٹی میں حیاتیاتی کیمیا ڈاکٹر ڈین جونز کہتے ہیں کہ معدے میں موجود خردبینی زندہ اجسام مثلاً بیکٹیریا وغیرہ اور موٹاپے کے درمیان تحقیق سے ہم اپنی غذائی ترجیحات اور اس فربہی کے علاج میں اہم پیشرفت کرسکتےہیں۔
گزشتہ کئی برس میں معدے اور نظامِ ہاضمہ میں موجود اہم خردنامیوں اور انکے دماغی امراض، عمومی صحت اور خود زندگی پر اثرات پر بہت سی نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں۔ اب ماہرین کا اصرار ہے کہ جیسے جیسے بعض مائیکروبس بڑھتے ہیں ویسے ویسے موٹاپا ایک وبا کی طرح ہمارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔
اگر موٹاپے کی اہم وجوہ کا جائزہ لیا جائے تو جینیاتی علوم، ماحولیات، رہن سہن، غذا اور سب سے بڑھ کر معدے کے خردنامیوں کا اس میں کردار اہم ہوتا ہے۔
چوہوں پر تحقیق کے بعد سائنسداں انسانوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ 214 افراد پر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ فربہ افراد کے خون میں ایک ڈیلٹا ویلروبیٹین کی زائد مقدار ہوتی ہے۔ بسا اوقات اس کی مقدار عام انسانوں میں 40 فیصد تک بڑھی ہوئی دیکھی گئی ہے۔
لیکن یاد رہے کہ بعض اقسام کے خردنامئے ڈیلٹا ویلروبیٹین کو بڑھاتے ہیں اور یہ ایک پیچیدہ عمل سے جسم میں چربی بڑھاتے رہتے ہیں۔ یعنی معدے اور آنتوں کے خردنامیوں اور ڈیلٹا ویلروبیٹین کے درمیان گہرا تعلق سامنے آیا جو ہمیں خاموشی سے موٹا بنائے جارہا ہے۔
لیکن اب بھی اس عمل کو مکمل طور پر سمجھنا باقی ہے تاکہ اس بنیاد پر موٹاپے پر قابو پانے والی کوئی تھراپی وضع کی جاسکے۔
https://www.express.pk/story/2281686/9812/
کینسر کے علاج میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ دوا براہِ راست رسولیوں یا سرطانی خلیات پر ڈالی جائے تب ہی بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے ایم آرآئی کی مدد سے مقناطیسی دانوں کو سرطانی پھوڑوں پر ڈال کر انہیں گرم کرکے کینسرختم کرنے کا انوکھا طریقہ پیش کیا ہے۔
یہ عمل قدرے آسان اور سادہ ہونے کے ساتھ خود مریض کے لیے بھی کم تکلیف دہ ہوسکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو ’منیمل انویزو امیج گائیڈڈ ایبلیشن‘ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں میگنیٹک ریزوننس امیجنگ (ایم آرآئی) سے مقناطیسی خواص والے باریک موتیوں کو دھکیل کر رسولی والے مقام تک لے جایا جاتا ہے۔ پھر منزل سے قبل انہیں گرم کرکے کینسر کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جاسکتا ہے۔
ایڈوانسڈ سائنس میں شائع رپورٹ کے مطابق اسے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر مارک لتھجو نے چوہوں پرآزمایا ہے۔ اسے انتہائی درست طریقہ علاج قرار دیا گیا ہے جس میں خردبینی شکل کے مقناطیسی دانے بدن میں داخل کرکے انہیں ایم آرآئی مشین کی بدولت باہر سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس طرح گرم کرنے کے بعد وہ کینسرکے خلیات کو ختم کرتے ہیں مگر تندرست خلیات کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان باریک دانوں کو تھرموسیڈز کا نام دیا گیا ہے جن کی زیادہ سے زیادہ موٹائی دو ملی میٹر ہوتی ہے۔
ایک اور سائنسداں، پروفیسر ریبیکا بیکر نے اسے باقاعدہ ایک تھراپی قرار دیا ہے۔ چونکہ ایم آرآئی عکس بندی میں جسم کے اندر کی تفصیلی عکس بندی سامنے آتی ہے اس لیے ماہرین مقناطیسی موتیوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی چیرپھاڑ کی ضرورت نہیں رہتی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے دماغ کے کینسر کے لئے ہی تیار کیا گیا ہے جس کا علاج کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔
چوہوں پر اس کے نہایت حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ تاہم اب بھی انسانوں پر آزمائش میں چند سال لگ سکتے ہیں۔
https://www.express.pk/story/2280827/9812/
مکڑی کے جالے کو اعصاب، رگوں اور پٹھوں کی مرمت اور اس کی نشوونما میں استعمال کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔
مکڑی کے جالا قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے جو زہریلے اثرات سے پاک، جراثیم سے دور اور حیاتیاتی طور پر بہت یکسانیت رکھتا ہے۔
جرمنی کی یونیورسٹی آف بائی روئٹ کےتھامس شائبل نے جینس قسم کی مکڑی کے جالے کو جینیاتی انجینیئرنگ کے عمل سے گزارا ہے۔ اس طرح بہت معیاری جالا حاصل ہوا جس کے پروٹین کو تبدیل کرنا ممکن تھا۔ سائنسداں چاہتے تھے کہ کسی طرح مکڑی کے جالے کو اعصابی خلیات کی نشوونما میں استعمال کیا جائے۔
اس کے لیے سائنسدانوں نے قدرتی جالے کو بایوٹیکنالوجی کے عمل سے گزارا ہے جس کے بعد دو مختلف اقسام کے پروٹین شامل کئے گئے ہیں اور ان کی مقدار اور تاثیر کو بڑھایا گیا ہے۔ مکڑی کے تار کے ریشوں کا ایک رخ سنگل امائنو ایسڈ سے بدلا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ پروٹین کا مجموعی چارج منفی سے مثبت ہوگیا۔ اس طرح یہ والی سطح خلیات کو زیادہ کشش کرنے لگی تھی۔
اب مکڑی کے ریشے کی دوسری جانب امائنو ایسڈ سسٹائن ملایا گیا۔ اس کے بعد کوئی بھی شے اس سے منسلک ہوگی تو اس میں ردِ عمل یعنی ری ایکشن بڑھ جاتا ہے۔
ماہرین نے جالے کے دونوں اطراف کو الیکٹرواسپننگ سے گزار کر پروٹین کو برقی فیلڈ کا حامل بنایا گیا اور اس میں سونے کے نینوذرات کا اضافہ بھی کیاگیا ہے۔
اس کے بعد خلیات پر ابتدائی آزمائش میں مکڑی کا تبدیل شدہ جالا لگایا گیا تو اس کے بہت امید افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔
https://www.express.pk/story/2280947/9812/
خلائی سائنس و ٹیکنالوجی میں قابلِ قدر خدمات اور دریافتوں کے بعد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کو آخرکار 2031 تک سمندر کی سمت پھینکا جائے گا اور توقع ہے کہ ہوائی رگڑ سے جلنے کے بعد بھی اس کا کچھ حصہ سمندر میں گرے گا۔
ناسا نے کانگریس کو پیشکردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے بعض حصے قابلِ مرمت ہیں لیکن آخرکار اسے ریٹائر کرنا ہی ہے۔ منصوبے کے تحت اسے بحرالکاہل کے ایک مقام ’پوائنٹ نیمو‘ میں گرایا جائے گا جو ایک غیرآباد اور ویران خطہ بھی ہے۔
ناسا کے مطابق پوائنٹ نیمو ایک ایسا علاقہ ہے جو آبادی سے بہت دور ہے اور یہاں 2001 میں روسی خلائی اسٹیشن میر کو بھی پھینکا گیا تھا۔ اس سے قبل بڑے بڑے سیٹلائٹ بھی اس رخ پر مدار بدر یعنی ڈی آربٹ کئے جاتے رہے ہیں۔ اسے ماہریں خلائی اجسام اور سیٹلائٹ کا قبرستان بھی کہتے ہیں۔
واضح رہے کہ کانگریس نے ناسا کے ماہرین سے کہا تھا کہ وہ اسٹیشن کے قابلِ عمل ہونے کے متعلق بتائیں اور یہ بھی کہ اس کا مستقبل کیا ہوسکتا ہے۔ اس پر ناسا نے کہا ہے کہ اس کا مدار مزید نیچے یعنی نچلے ارضی مدار تک کھسکھا کر اسے نجی کمپنیوں کے حوالے کیا جاسکتا ہے لیکن آخر کار طے پایا کہ نو برس بعد اس کا رخ زمین ہی ہوگا۔
1998 سے آئی ایس ایس خلا میں رہتے ہوئے زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ اسے دنیا کے پانچ خلائی اداروں نے بنایا تھا اور 2000 سے یہاں انسانوں کی آمدورفت جاری ہے۔ اس کی مشہور خردثقلی تجربہ گاہ میں 3000 سے زائد انوکھے اور دلچسپ تجربات کئے گئے جو زمینی ماحول میں ممکن نہ تھے۔ اس طرح ہم نےبہت سی نئی ٹیکنالوجی بھی وضع کیں جو عشروں تک انسانوں کے کام آتی رہیں گی۔
منصوبے کے تحت 2030 تک اس کے معمول کے آپریشنز جاری رہیں گے جبکہ اسے بتدریج بند کرکے مکمل خاموش کردیا جائے گا۔ اس کے بعد اسے مدار سے بے دخل کیا جائے گا جو کئی مراحل میں ممکن ہوسکے گا۔
https://www.express.pk/story/2280969/508/
ہالینڈ میں دریافت ہونے والا ایچ آئی وی کی نئی تغیرشدہ قسم کی تصدیق ہوگئی ہے جس کے اولین ثبوت ہالینڈ سے ملے ہیں۔
سائنسدانوں کے مطابق ایڈز کی وجہ بننے والے بدنامِ زمانہ ایچ آئی وی کی ایک نئی تبدیل شدہ قسم ہالینڈ کے علاوہ دیگر یورپی ممالک میں عشروں سے موجود ہوسکتی ہے۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق اس کا پھیلاؤ شدید ہے، وائرس مرض کو تیزتر کرتا ہے لیکن ایڈز کی روایتی ادویہ سے اس کا علاج ممکن ہے۔
ہم جانتے ہیں ہیومن امیونیوڈیفی شنسی وائرس (ایچ آئی وی) انسانی بدن میں داخل ہونے کے بعد ’اکوائرڈ امیونٹی ڈیفی شنسی سنڈروم‘ (ایڈز) کی وجہ بنتا ہے۔ اس میں جسم کا دفاعی امنیاتی نظام بہت کمزور ہوجاتا ہے اور ہر قسم کے امراض کی راہ کھل جاتی ہے لیکن ایڈز کی اپنی علامات اور عارضوں کی فہرست طویل ہوتی ہے ۔ اگرعلاج نہ کرایا جائے تو مریض موت کے منہ میں چلاجاتا ہے۔
روایتی ایچ آئی وائرس سی ڈی فور ٹی سیل کو تباہ کرتا ہے جو بہت اہم امنیاتی خلیات ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس نئے تبدیل شدہ ویریئنٹ کو وی بی کا نام دیا گیا ہے۔ وی بی کا نشانہ بننے والے لگ بھگ 100افراد پر تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ بالخصوص عمررسیدہ افراد پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ عام وائرس کے مقابلے میں یہ سی ڈی فور خلیات کو قدرے تیزی سے ختم کرتا ہے۔
ماہرین کے مطابق عام حالات میں اگر ایچ آئی وی بدن میں آگھسے تو وہ چھ سے سات سال میں ایڈز کا مریض بنادیتا ہے بشرطیکہ کہ علاج نہ کروایا جائے۔ لیکن وی بھی صرف دو سے تین برس میں مریض بناسکتا ہے۔
تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری روایتی دوائیں ہی اس ویریئنٹ کا علاج کرسکتی ہیں۔
https://www.express.pk/story/2280687/9812/
وہ دن دور نہیں جب ذیابیطس کے مریض نسوار کی طرح گال کے اندر اسٹیکر نما پیوند لگا کر انسولین کی مناسب مقدار بدن کے اندر شامل کرکے خون میں گلوکوز کنٹرول کرسکیں گے۔
فی الحال انسولین کی خوراک ٹیکوں یا پمپ سے جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ لیکن اب فرانس کی یونیورسٹی آف لیلے کی پروفیسر سبینے زیونیرائٹس اور دیگر ممالک کے ساتھیوں نے ایک تجرباتی پیوند بنایا ہے۔ اس میں انسولین دوا کے طور پر شامل ہے اور گال کے اندر چپک کر خون میں انسولین داخل کرسکتی ہے۔
یہ نرم پیوند تین اشیا پر مشتمل ہے۔ ایک تو اسے پولی ایکریلک ایسڈ نامی پالیمر کے نینوفائبر سےبنایا گیا ہے۔ پھر اس میں بی ٹا سائیکلو ڈیکسٹرن سالمہ یعنی مالیکیول ملایا گیا ہے اور آخر میں گرافین آکسائیڈ کی کچھ مقدار شامل کی گئی ہے۔
اگلے مرحلے میں اس کے چھوٹے ٹکڑوں کو انسولین محلول میں تین گھنٹے تک ڈبویا گیا۔ اس کے بعد انہیں خنزیروں کے گال کے اندر موجود کھال کی تہوں پر لگایا گیا۔ انفراریڈ لیزر سے انہیں 50 درجے سینٹی گریڈ تک دس منٹ تک گرم کیا گیا۔
سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسولین کا اخراج ہوا اور وہ جلد کے اندر جذب ہونے لگے۔ اس کے بعد تین خنزیر ایسے لئے گئے جو ذیابیطس کے مریض تھے۔ پھر پیوند کو بیرونی طور پر دس منٹ تک گرم کیا گیا اور وہ انسولین خارج کرنے لگے۔ ہرجانور کو دس دس منٹ تک پیوند لگایا گیا۔ ماہرین نے نوٹ کیا کہ فوری طور پر ان کے خون میں شکر کی مقدار کم ہونے لگی اس طرح صرف 20 منٹ میں انسولین کی پوری خوراک جسم کے اندر پہنچ گئی۔
گال کے اندر لگائے جانے والے اسٹیکر سے جلد پر کوئی خراش یا منفی اثر نہ ہوا۔ اسی طرح کے فرضی پیوند چھ انسانوں کو دو گھنٹے تک لگائے گئے تو ان کے اندر کوئی منفی اثر نہ ہوا۔
اگلے مرحلے میں منہ کے اندر انسولین پیوند نظام کی مزید آزمائش کی جائے گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک اسٹیکر میں بار بار انسولین بھری جاسکتی ہے۔
https://www.express.pk/story/2280282/9812/
دُنیا اتنی تیزرفتاری سے بدل رہی ہے کہ عام انسان کا اس رفتار کے ساتھ چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے ۔
ٹیکنالوجی کی ترقی نے اس ترقی کی رفتار کو مزید تیز کردیا ہے۔ نئی ایجادات اور مہارتوں میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ خود کو اس بدلتے دور میں اپ ڈیٹ رکھنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ عملی ذہانتIQ اور جذباتی ذہانت EQ نے جہاں انسانی نفسیات اور رویوں کو سمجھانے میں مدد دی ہے وہاں ٹیکنالوجی کے انقلاب اور اثرات کو سمجھنے کے لیے ڈیجیٹل انٹیلی جینس DQ نے ایک نیا انقلاب برپا کردیا ہے۔
یہ ڈیجیٹل انٹیلی جینس کیا ہے، کیوں ضروری ہے اور اس سے واقفیت ہماری دُنیا کو محفوظ اور بہتر بنانے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس آرٹیکل میں اس پر بات کریں گے۔
ڈیجیٹل انٹیلی جینس ایک ایسی دُنیا میں بہت ضروری ہوگئی جو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب تیزی سے گام زن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز (ICT) سے متعلق مہارتوں اور قابلیت کو فروغ دینا، اسمارٹ فون یا ٹیبلیٹ کے استعمال کے بارے میں جاننے سے کہیں بڑھ کر ہے۔
معاشرے کے لیے بالخصوص شعبۂ تعلیم کے لیے یہ خاص ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے کیوںکہ بچوں کو ڈیجیٹل ذہانت فراہم کرنا والدین اور اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلینج ہے۔
آج کی دُنیا 20 سال پہلے جیسی نہیں رہی اور نہ ہی آنے والے کل کی دُنیا آج جیسی ہوگی۔ ڈیجیٹلائزیشن نے ہمارے سوچنے، محسوس کرنے اور رہنے کے انداز کو یکسر تبدیل کردیا ہے اور اس کا ارتقاء اتنا گھما دینے والا ہے کہ جو تبدیلی کبھی ناممکن لگتی تھی اب معمول بن گئی ہے۔ لہٰذا تبدیلی کا انتظام21 ویں صدی میں لوگوں کے لیے ایک بنیادی مہارت کے طور پر ابھرا ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم ڈیجیٹل ذہانت کی تعلیم ہے۔
تعلیم کی ڈیجیٹائزیشن: ایک نئے دُور کا آغاز
تعلیم ان شعبوں میں سے ایک ہے بلکہ سب سے نمایاں ہے جس میں ڈیجیٹلائزیشن کا سب سے زیادہ اثر ہوا ہے۔ آئی سی ٹی کو کلاس رومز اور گھروں میں شامل کیا گیا ہے لیکن ان ٹولز کے علاوہ اہم سوال یہ ہے کہ ’’ہم لوگوں کو آج اور کل کی دُنیا کے لیے کیسے تعلیم دے سکتے ہیں؟‘‘ کیوںکہ ڈیجیٹل انٹیلی جینس کی ترقی موبائل فون کو چلانے سے بہت آگے کی تعلیم اور سوچ ہے۔ یہاں اہم نقطہ نظر لوگوں کو ڈیجیٹل زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے۔
انٹرنیٹ نے تعلیم تک رسائی کو عالم گیر بنا دیا ہے لیکن ڈیجیٹل تقسیم کی وجہ سے یہ سہولت ہر جگہ برابر نہیں ہے۔ آن لائن تعلیم کا سلسلہ معمول کی تعلیم کا ایک طرح سے متبادل بن گیا ہے جس نے نہ صرف COVID-19 کے دوران کلاسوں کو جاری رکھنے میں مدد کی ہے بلکہ زندگی بھر سیکھنے کے عمل کو فروغ دیا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کام کی ذمے داریوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس امر نے ہمیں ایک ایسی دُنیا میں داخل کردیا ہے جو ہمیں زندگی بھر مسلسل سیکھنے کی طرف دھکیل رہی ہے۔
ڈیجیٹل انٹیلی جینس کیا ہے؟
2016 میں DQ انسٹی ٹیوٹ نے یہ اصطلاح تیار کی (جس کی بنیاد پر بعد میں ورلڈ اکنامک فورم نے #DQEveryChild Movement کا آغاز کیا)، جس کے مطابق ڈیجیٹل انٹیلی جینس ’’سماجی، جذباتی اور علمی مہارتوں کا مجموعہ ہے، جو لوگوں کو ڈیجیٹل زندگی کے چیلینجوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل بناتا ہے۔‘‘ ڈیجیٹل انٹیلی جینس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ چیلینجز ہمارے استعمال کردہ آلات کی وجہ سے نہیں بڑھتے بلکہ ان تجربات کی وجہ سے درپیش ہوتے ہیں جن تک وہ ہمیں رسائی دیتے ہیں۔
ڈیجیٹل انٹیلی جینس ڈیجیٹل مہارتوں اور ڈیجیٹل پروفائلز کو تیار کرنے کے لیے اہم ہوگئی جس کا اس صدی میں بھرپور تقاضا ہے۔ اس لیے ماہرین کا مقصد آئی سی ٹی کو ایک نئے تعلیمی پلیٹ فارم کے طور پر سوچنے سے آگے بڑھنا ہے اور اپنے طلبہ کی ایسی دُنیا میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے جہاں ڈیجیٹل میڈیا ہمیشہ سے موجود ہے۔
جس طرح ہم جنرل انٹیلی جینس (IQ) اور جذباتی ذہانت (EQ) کی پیمائش کر سکتے ہیں اسی طرح DQ انسٹی ٹیوٹ کا دعویٰ ہے کہ ڈیجیٹل انٹیلی جینس (DQ) کو بھی ناپا جا سکتا ہے۔ اسے انتہائی کم عمر میں زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ڈیجیٹل انٹیلی جینس کے ذریعے سائبر کرائم، فیک نیوز، معلومات کی چوری یا غلط معلومات (جعلی خبروں) جیسے خطرات سے موثر انداز میں نبردآزما ہو جا سکتا ہے۔
ڈیجیٹل انٹیلی جینس کی سطحات اور صلاحیتیں ہیں جن پر عبور حاصل کرکے ایک محفوظ اور بہتر ڈیجیٹل زندگی بسر کی جاسکتی ہے۔ ڈیجیٹل ذہانت کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے:
لیول 1: ڈیجیٹل شہریت جو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل میڈیا کو محفوظ، ذمے داری اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔
لیول 2: ڈیجیٹل تخلیقی صلاحیت جس میں ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال سے نیا مواد تخلیق کرنے اور آئیڈیاز کو حقیقت میں بدلنے کا فن سیکھا جا سکتا ہے۔
لیول 3۔ ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں عالمی چیلینجوں کو حل کرنے یا نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ڈیجیٹل انٹیلی جینس کی متعدد صلاحیتیں ہیں جن کو سیکھنا انتہائی اہم ہے۔
ڈیجیٹل شناخت: اس میں آپ اپنی آن لائن شناخت اور ساکھ بناتے ہیں اور خود کی آن لائن شخصیت کو سمجھنے اور اپنی آن لائن موجودگی کے مختصر اور طویل مدتی اثرات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔
ڈیجیٹل استعمال: اپنی آن لائن اور آف لائن زندگی کے درمیان صحت مند توازن برقرار رکھنے کے لیے خوداحتسابی سمیت آسانی کے ساتھ ڈیجیٹل آلات اور میڈیا کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔
ڈیجیٹل سیکیوریٹی: اس میں آپ کو آن لائن خطرات سے بچنے اور اس کے اثرات کو محدود کرنے (سائبر کرائم، گرومنگ، بنیاد پرستی، وغیرہ) کے ساتھ مسائل والے مواد (پرتشدد یا فحش مواد) سے بچنے کے ٹول سکھائے جاتے ہیں۔
ڈیجیٹل تحفظ: سائبر خطرات (پائریسی، گھوٹالے، مالویئر وغیرہ) کا پتا لگانے کے بہترین طریقوں کو سمجھنے اور ڈیٹا کے تحفظ کے لیے مناسب حفاظتی ٹولز استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔
ڈیجیٹل جذباتی ذہانت: اس میں صارفین کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے ہم درد بنیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ صحت مند آن لائن تعلقات استوار کریں۔
ڈیجیٹل مواصلات: ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور تعاون کو یقینی بنایا جاتا ہے۔
ڈیجیٹل خواندگی: اس صلاحیت میں مواد تلاش کرنے، جانچنے، استعمال کرنے ، شیئر کرنے اور تخلیق کرنے اور کمپیوٹیشنل سوچ کو تیار کیا جاتا ہے۔
ڈیجیٹل حقوق: یہ ڈیجیٹل حقوق کو سمجھنے اور ان کا دفاع کرنے کے بارے میں ہے۔ (جیسے پرائیویسی، دانش ورانہ املاک، اظہاررائے کی آزادی اور نفرت انگیز تقریر کے خلاف تحفظ)۔
ہم ڈیجیٹل انٹیلی جینس کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟
جیسے جیسے چوتھا صنعتی انقلاب آگے بڑھ رہا ہے جس سے ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں دُنیا بھر کے معاشروں کی صحت اور خوش حالی کا انحصار ڈیجیٹل انٹیلی جینس پر بڑھتا جائے گا۔ بچے پہلے ہی ڈیجیٹل دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی انگلیوں پر ہے اور وہ کل کی دُنیا کی وضاحت کریں گے، لیکن ایسا کرنے کے لیے انہیں ضروری مہارتوں سے لیس ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پورے معاشرے، سرکاری اور نجی شعبوں کو مل کر کام کرنا ہو گا۔
ریاست کو ڈیجیٹل معاشرے کی بنیاد پر ڈیجیٹل ذہانت کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنے شہریوں کی ڈیجیٹل صلاحیتوں کو فروغ دینے والے پروگراموں کو نافذ کرنے پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اسے تعلیمی نظام میں موجود خلاء کو پر کرنا ہوگا اور انہیں وسائل اور مہارت فراہم کرنی ہوں گا۔ ڈیجیٹل دُنیا بے شمار مواقع فراہم کرتی ہے لیکن یہ والدین اور اساتذہ کے لیے تشویش کا باعث بھی ہے۔
لہٰذا تعلیم کا آغاز بچوں کے اثرورسوخ کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ گھر میں ان کے والدین اور اسکول میں اساتذہ اس عمل کی نگرانی کریں۔ تشخیص کے مواقع جو بچوں کو اپنی خوبیوں اور کم زوریوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی صلاحیت دیتے ہیں کام یابی کی طرف راہ نمائی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
ڈیجیٹل انٹیلی جینس نوجوانوں کو اچھے ڈیجیٹل شہری بنانے کے لیے ان لوگوں کو ان صلاحیتوں سے لیس ہونے کی ضرورت ہے جن کی جڑیں عالم گیر اخلاقی اقدار میں پوست ہیں تاکہ وہ اچھے ڈیجیٹل شہری بن سکیں۔ ان کی باخبر انتخاب کرنے میں مدد کریں اور ڈیجیٹل دُنیا میں محفوظ طریقے سے سرگرم رہنے کے لیے راہ نمائی کریں۔ ڈیجیٹل انٹیلی جینس پلیٹ فارم کا مقصد بچوں کو ڈیجیٹل شہریت، اخلاقی کردار اور تنقیدی سوچ سکھانا اور جانچنا ہے۔
ڈیجیٹل انٹیلی جینس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ ڈیجیٹل انٹیلی جینس کونٹینٹ (DQ) سب سے پہلے تیار کیا گیا تھا اور اس کا فریم ورک 2016 میں ڈاکٹر یوہیون پارک نے بنایا تھا۔ اسے مختلف یونیورسٹیوں بشمول نانیانگ ٹیکنولوجیکل یونیورسٹی، سنگاپور میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن، آئیووا اسٹیٹ یونیورسٹی اور بہت سی دیگر یونیورسٹیوں میں قائم تحقیقی ٹیم کے ذریعہ ایک تعلیمی لحاظ سے سخت عمل کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔
اس کے تصور اور ڈھانچے کو ورلڈ اکنامک فورم نے 2016 میں شائع کیا تھا اور اس کے بعد سے DQ فریم ورک کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بے شمار صنعتوں اورتنظیموں کے ذریعے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
اس ساری صورت حال کو جانتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی بلکہ موجودہ نسلوں کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کیوںکہ ہم اس کا اندازہ اپنے گھروں میں بچوں کا موبائیل فون پر کارٹون دیکھنے اور اسکلرلنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔
ہم ہمیشہ دُنیا میں آنے والے تبدیلوں کو دیر سے اپناتے ہیں لیکن یہ تبدیلی بہت تیز ہے اس میں ایک سال کی دیر دس سال کے برابر ہے۔ اپنے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹوں میں اس ضمن میں زیادہ سے زیادہ آگاہی اور شعور دینے پر زور دینا ہوگا۔ سوچ کو بدلنے اور وقت کی ضرورت کو سمجھنا ہو گا۔ والدین اور اساتذہ کو اپنے بچوں کی خوب صورت دُنیا کو محفوظ بنانے کے لیے چند اہم نکات پر عمل کرنا چاہیے۔
بچوں کی یہ سوچنے میں مدد کریں کہ وہ کیا شیئر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بچے جو کچھ شیئر کر رہے ہیں اس کا نقطہ آغاز یہ ہونا چاہیے۔ کیا بچے جانتے ہیں کہ وہ مناسب ہے؟ اس طرح کی گفتگو کرنے سے آپ کو بچوں کو دُنیا تک رسائی ان کی انگلی پر رکھنے سے پہلے اس کے بنیادی اصول طے کرنے میں مدد ے گی۔ والدین کی نگرانی کا اہم کردار ہے کیوںکہ بچوں کے سامنے بہت زیادہ نامناسب مواد موجود ہے۔
تاہم صحیح معلومات کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں لازمی کریں۔ مانیٹرنگ سافٹ ویئر انسٹال کرنے جیسے اقدامات کریں۔ بچوں کو اپنے تجربات کے بارے میں بتائیں۔ آن لائن کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپنے بچوں سے بات کریں۔ جب آپ بات کرنے میں وقت گزارتے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ آپ کے بچے کیسے سوچتے ہیں۔
یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی معلومات تک رسائی حاصل ہے کیوںکہ وہ ہوم ورک کے لیے انٹرنیٹ اور گوگل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس بارے میں بات کریں کہ وہ اپنا دوست کسے کہتے ہیں۔ معلوم کریں کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آن لائن کیا گفتگو کرتے ہیں۔ بحیثیت والدین اپنے بچوں کے دوستوں کے ساتھ بھی چیٹنگ میں وقت گزاریں۔ والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کو تحقیق کرنی چاہیے اور جاننا چاہیے کہ انٹرنیٹ کی دُنیا میںکیا ہو رہا ہے۔
ان کو تمام نئے رجحانات اور اثرات سے زیادہ واقف ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل انٹیلی جینس ایک پرکشش دُنیا ہے جس سے کوئی بھی انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے اس سے بھرپور واقفیت ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنی مثبت شنا خت بنا سکیں اور محفوظ دُنیا کا حصہ بن سکیں۔
https://www.express.pk/story/2277443/508/
کائنات اور اس میں سمائی ہوئی ہر شے کے بارے میں انسان کی تفہیم سائنسی علوم کی رہین منت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ کائنات کے ہر پہلو کے بارے میں انسانی تفہیم وسیع تر ہوتی جارہی ہے۔ اس ترقی کی بنیاد پر نت نئی دریافتیں، ایجادات، انکشافات اور اختراعات ہورہی ہیں۔
2021ء میں بھی سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ کووڈ 19 کے باعث ٹیکنالوجی کی دنیا میں نئے رجحانات بھی متعارف ہوئے۔ مندرجہ ذیل سطور میں گذشتہ برس ہونے والی کچھ ایسی ہی اہم دریافتوں، اختراعات ، رجحانات اور پیش رفتوں کا جائزہ لیا جارہا ہے، سائنسی افق پر جن کے اہم اثرات مرتب ہوئے۔
کووڈ 19 / ای کامرس
کووڈ 19کی وبا 2020ء کی طرح 2021ء میں بھی دنیا بھر میں چھائی رہی۔ گذشتہ برس کے ابتدائی مہینوں میں کورونا کا زور ٹوٹ چکا تھا اور دنیا کے بیشتر ممالک میں کووڈ 19 کی احتیاطی تدابیر کے طور پر عائد کی گئی پابندیاں مکمل یا جزوی طور پر ختم ہوچکی تھیں۔ تاہم سال کے دوسرے نصف میں کورونا شکل بدل کر ’’ اومی کرون‘‘ کی صورت میں ایک بار پھر شدت سے حملہ آور ہوا۔ جنوبی افریقا سے شرو ع ہونے والی کووڈ 19 کی یہ قسم تقریباً دنیا بھر میں پھیل چکی ہے اور بتدریج ایک بار پھر عالمی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جارہی ہیں۔
2020ء میں کورونا نے ای کامرس کے شعبے میں گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ لاک ڈائون کی وجہ سے بالخصوص آن لائن خریداری کے رجحان میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ گذشتہ برس اس رجحان میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے خریداری کرنے والے صارفین کی تعداد نمایاں طور پر بڑھ گئی۔ کورونا کے باعث متعدد وہ کاروبار بھی آن لائن ہوگئے جو پہلے نہیں تھے۔ اب گھریلو سوداسلف سے لے کر ہوائی جہازوں کے ٹکٹ تک ہر شے آن لائن خریدی اور بیچی جارہی ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق بین الاقوامی اسٹورز کی آن لائن فروخت میں 2021ء کے دوران 10 فی صد اضافہ ہوا۔
مریخ؍ اہم سنگ میل
2021ء میں ارض مریخ کو مزید دو خودکار تحقیقاتی مشینوں ( ایکسپلوررز) نے چُھوا۔ جدید آلات سے لیس ان تحقیقاتی خلائی مشینوں میں ناسا کا ’پریزرویرنس‘ اور چین کا ژورونگ روور شامل تھا۔ پریزرویرنس 18 فروری اورژورونگ 14 مئی کو سرزمین مریخ پر کام یابی سے اترا۔ چین کے لیے یہ مشن اس لحاظ سے یادگار تھا کہ یہ پہلا موقع تھا جب اس کا خلائی جہاز کسی دوسرے سیارے پر اترا ہو۔ زمین کے ہمسائے پر ان خودکار تحقیقاتی گاڑیوں کے اترنے کا مقصد بھی اس سیارے پر زندگی کا کھوج لگانا ہے۔ مریخ عشروں سے سائنس دانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جن کا خیال بلکہ یقین ہے کہ ماضی میں مریخ ایک زندہ سیارہ تھا، یہاں دریا اور سمندر رواں تھے اور زندگی مختلف اشکال میں چہار سُو پائی جاتی تھی۔
پریزرویرنس کی لینڈنگ سے ناسا نے مریخ کے حوالے سے کئی سنگ میل حاصل کیے۔ 19 اپریل کو پریزرویرنس سے منسلک Ingenuity ہیلی کاپٹر نے سرخ سیارے کی فضا میں پرواز کی۔ یہ کسی بھی دوسری دنیا میں انسانی کنٹرول سے ہونے والی اولین پرواز تھی۔
اگلے ہی روز تحقیقاتی گاڑی پر نصب آلات نے مریخ کی فضا میں بھری کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کچھ مقدار کو پہلی بار آکسیجن میں تبدیل کردیا۔ اس کام یابی کے بعد مستقبل کے خلانوردوں کے لیے ایندھن اور سانس لینے کے لیے آکسیجن حاصل کرنے کی راہ ہموار ہوگئی۔ بعدازاں ستمبر میں پریزرویرنس نے زمین پر بھیجنے کے لیے مریخ کی مٹی کے نمونے حاصل کیے۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس اہم ترین پیش رفت کے بعد مریخ سے جُڑی ہر سائنسی شے تبدیل ہوجائے گی۔
نئی نوع انسانی کی دریافت
انسانی رکازوں (فوسل) کی دو دریافتوں کے بعد شجرۂ انسانی کی گتھیاں مزید الجھ گئیں۔ پہلی دریافت چین میں ہوئی، جہاں ایک متروک کنویں کی تہہ میں سے ایک انسانی کھوپڑی محفوظ حالت میں دریافت ہوئی۔ سائنسی تحقیق سے واضح ہوا کہ کھوپڑی 146000 سال قدیم تھی اور اس میں قدیم اور جدید انسانوں کی خصوصیات کے آثار پائے گئے۔
یہ کھوپڑی اس انسان یا انسان نما مخلوق (hominin) کی تھی جو اپنی ہیئت میں نیندرتھلز ( قدیم انسان) کی نسبت ہم سے زیادہ قریب تھا۔ کچھ محققین کا خیال تھا کہ یہ کھوپڑی ایک نئی نوع انسانی کی نمائندہ ہوسکتی ہے جسے انھوں نے Homo longi یا ’ڈریگن مین‘ کا نام دیا۔ اس دریافت کے بعد تحقیقی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑگئی کیوں کہ محققین کے دوسرے گروپ کی رائے میں ’ڈریگن مین‘ اور نیندرتھلز کی ایک پراسرار شاخ کے مابین غیرمعمولی مشابہت پائی جاتی ہے جسے Denisovans کہا جاتا ہے۔ گذشتہ برس جون میں محققین کو اسرائیل میں ایک انسانی کھوپڑی اور جبڑے کے کچھ ٹکڑے ملے جو 120000 سے 140000 سال قدیم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہومینن اور ہومو سیپیئن ( ایک نوع انسانی ) کا تعلق ایک ہی زمانے سے تھا اور ان میں باہم رابطہ کاری بھی تھی۔
کووڈ 19ویکسین کی منظوری
کورونا کی عالمی وبا کے خلاف جنگ میں 23اگست کو اس وقت انتہائی اہم پیش رفت ہوئی جب امریکا کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) نے فائزر کی بایواین ٹیک ویکسین کو منظور کرلیا۔ اس پر جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پبلک ہیلتھ پروفیسر لینا وین نے کہا کہ اس اقدام سے ہم امریکا میں وبا کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہوجائیں گے۔
انسانی جینوم کی تکمیل
دو عشرے قبل سائنس دانوں نے انسانی جینوم کی سیکونسنگ (نقشہ سازی) کا دھماکا خیز اعلان کیا تھا۔ تاہم یہ سیکونس مکمل نہیں تھا۔ برسوں کی محنت کے بعد بھی ہمارا 8 فی صد جینیاتی کوڈ سائنس دانوں کی گرفت میں نہیں آرہا۔ تاہم گذشتہ برس مئی میں محققی نے انسانی جینوم کا ’پہلا حقیقی طور پر مکمل‘ سیکونس تیار کرنے کا اعلان کیا۔ سائنس دانوں کے مطابق یہ سیکونس 23 کروموسوم اور 3.055 ارب بنیادی جوڑوں (بیس پیئرز) پر مشتمل ہے۔ اس تحقیق نے سابقہ تحقیق میں 20 کروڑ بیس پیئرز کا اضافہ کیا اور جینوم کے سابقہ تجزیوں میں متعدد ترامیم کیں۔ سائنس دانوں نے اس تحقیق کو اہم پیش رفت قرار دیا۔
براعظم شمالی اور جنوبی امریکا میں انسانی آمد کے آثار
ان براعظموں میں انسان کی آمد کب ہوئی؟ سائنس داں طویل عرصے سے اس بارے میں تحقیق کررہے ہیں۔ نیومیکسیکو کے وائٹ سینڈز نیشنل پارک میں ایک قدیم جھیل کے کنارے ایک پائوں کا رکاز (فوسل) دریافت ہوا ہے۔ کسی نوجوان کے پائوں کا یہ نشان اس خطے میں انسان کی آمد کے بارے میں سائنس دانوں کے اب تک کے اندازوں کو چیلنج کررہا ہے۔ بیشتر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ براعظم انسانی قدموں سے پہلی بار 13000 سال قبل آشنا ہوئے تھے۔ تاہم اس دریافت پر تحقیق کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ براؑعظم شمالی اور جنوبی امریکا میں انسانی آمد 21000 تا 23000سال قبل ہوئی۔
ملیریا ویکسین کی توثیق
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اکتوبر میں پہلی بار ملیریا ویکسین کی توثیق کردی جس کے بعد اس ویکسین کے دنیا بھر میں استعمال کے لیے اقدامات شروع کردیے گئے۔ ملیریا کا سبب ایک طفیلیہ بنتا ہے جو اس سے متاثرہ مچھروں کے کاٹنے کے ذریعے انسانی جسم میں منتقل ہوجاتا ہے ۔ ملیریا ہلاکت خیز مرض ہے۔ 2020ء میں ملیریا سے دنیابھر میں 627000 افراد ہلاک ہوئے جن میں 80 فیصد 5سال سے کم عمر کے بچے تھے۔
Mosquirix نامی یہ ویکسین ملیریا سے 56 فی صد تک تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ تحفظ کی یہ شرح دوسرے امراض کی ویکسین سے کم ہے تاہم ماہرین نے اس ویکسین کو ملیریا سے جنگ میں اہم ہتھیار قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ویکیسن کے ساتھ ساتھ ملیریا سے بچائو کے دیگر حفاظتی اقدامات اسی طرح کیے جانے چاہییں جیسے مچھردانی کا استعمال اور حشرات کش اسپرے وغیرہ۔
دنیا بھر میں کووڈ 19 ویکسین کا استعمال
دسمبر 2020ء میں وہ اہم ترین لمحہ آیا جب اس مہلک وبا سے تحفظ کے لیے دنیا بھر میں ویکسین کے استعمال کی شروعات ہوئی۔ 2021ء کے اختتام تک دنیا بھر میں کئی ارب انسانوں کو مختلف کووڈ 19 ویکسین لگائی جاچکی تھیں۔ 2 دسمبر 2020ء کو برطانیہ نے فائزر کی بایو این ٹیک ویکسین کے استعمال کی منظوری دی۔ چند روز بعد امریکا نے ہنگامی طور پر موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسز کی ویکسین کا استعمال منظور کرلیا۔
بعدازاں آنے والے مہینوں میں بتدریج دنیا بھر میں کووڈ سے بچائو کے ٹیکے ( ویکسین) لگوانے کی مہمات شروع ہوتی چلی گئیں۔ اس دوران ان ویکسین کی افادیت پر سوالات بھی اٹھائے گئے۔ ویکسین کی فراہمی میں مشکلات بھی پیش آئیں، تاہم ویکسی نیشن کا سلسلہ جاری رہا اور دسمبر 2021ء کے اختتام تک آٹھ ارب سے زائد افراد یعنی دنیا کی نصف کے لگ بھگ آبادی کو ویکسین لگائی جاچکی تھی۔ تاہم تشویشناک امر یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک میں کورونا ویکسین کی مجموعی خوراکوں کا صرف 6 فی صد پہنچ پایا۔
کائناتی دھماکے
ایک ارب سال قبل ایک بلیک ہول ایک مُردہ ستارے کی باقیات سے ٹکرایا تھا۔ اس تصادم کے نتیجے میں زماں و مکاں کے غلاف میں لہریں پیدا ہوئی تھیں جنھیں امواج ثقل کہا جاتا ہے۔ جنوری 2020ء میں سائنس دانوں نے اس غیرمعمولی اثر کی نشان دہی کی۔ دس روز کے بعد محققین کو خلائے بسیط میں اسی نوع کے ایک اور واقعے کا سراغ ملا۔
2015ء میں سائنس دانوں نے پہلی امواج ثقل کا سراغ لگایا تھا جو سوا ارب نوری سال کی دوری پر موجود دو بلیک ہولز کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک محققین بلیک ہولز اور مُردہ ستاروں کے درمیان تصادم کے 50 واقعات کی وقوع پذیری کا ثبوت ثقلی موجوں کی صورت میں حاصل کرچکے ہیں۔ تاہم گذشتہ برس پہلی بار ایک بلیک ہول اور نیوٹران اسٹار کے درمیان ادغام کی تصدیق کرپائے۔ ماہرین نے اسے خلائے بسیط میں جاری سرگرمیوں سے آگاہی حاصل کرنے کی جانب انتہائی اہم پیش رفت قرار دیا۔
جسم انسانی میں سؤر کے اعضا کی پیوندکاری
اکتوبر 2021ء میں سائنس دانوں نے انسان میں ایک ایسے گردے کی پیوندکاری کی جسے جینیاتی طور پر تبدیل کیے گئے سور کے جسم میں اُگایا گیا تھا۔ یہ گُردہ اس انسان کے جسم میں دو دن سے زائد عرصے تک بالکل صحیح کام کرتا رہا تھا۔ یہ انوکھا آپریشن نیویارک یونی رسٹی کے سرجن رابرٹ منٹگمری نے سرانجام دیا تھا۔ اس آپریشن کو غیرانسانی مخلوق سے انسان میں خلیوں، نسیجوں، یا اعضا کی پیوندکاری کے میدان (xenotransplantations) میں اہم پیش رفت قرار دیا جارہا ہے۔
مستقبل میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ سؤر ضرورت مند مریضوں کو اعضا کی فراہمی کا اہم ذریعہ ثابت ہوسکتے ہیں۔ تاہم یہ ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ سرجن رابرٹ اور ان کے ساتھیوں نے یہ تجربہ ایک دماغی طور پر مُردہ شخص پر اس کے اہل خانہ کی اجازت سے کیا تھا۔ یہ مریض وینٹی لیٹر پر تھا۔ ڈاکٹروں نے مشاہدہ کیا کہ گردہ دو دن سے زائد وقت تک مریض کے جسم میں فعال رہا تھا۔
مِلکی وے سے باہر سیارے کی دریافت
دو کروڑ 80 لاکھ نوری سال کی دوری پر واقع ’وھرل پول‘ نامی کہکشاں میں ماہرین فلکیات نے سیارہ دریافت کیا جسے اب تک دریافت شدہ بعید ترین سیاروں میں شمار کیا گیا۔ ایک ستارے کے گرد گردش کرتا یہ نیوٹران ستارے یا بلیک ہول کے مانند انتہائی کثیف ہے۔ اس کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ یہ ستارے کی گیس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس سیارے کا درجۂ حرارت بڑھ جاتاہے اور پھر یہ ایکس ریز خارج کرتا ہے۔
مصر میں قدیم شہر الاقصر کی دریافت
ستمبر 2020ء میں ماہرین آثارقدیمہ کو مصر کے صحرائوں میں ایک شہر کے آثار ملے تھے۔ اپریل 2021ء میں ماہرین آثار قدیمہ نے ان آثار کو قدیم مصری شہر الاقصر کے کھنڈرات قرار دیا۔ یہ شہر ساڑھے تین ہزار سال قبل فرعون مصر طوطن خامن کے دادا آمن ہوتب سوم نے آباد کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس شہر کی دریافت قدیم مصری تاریخ کے نشیب و فراز کو جاننے میں معاون ہوگی۔
آمن ہوتب سوم کی موت کے بعد اس کا بیٹا تمام دیوتائوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی دیوتا (سورج) کو پوجنے لگا تھا۔ اس نے دارالحکومت تھیبس چھوڑ دیا تھا۔ نودریافت شدہ شہر اسی کا حصہ تھا۔ ماہرین کے مطابق الاقصر کی دریافت اس دور کی سلطنت فراعنہ، ان کے اختیار و طاقت اور اس زمانے کی ثقافت کی جانب ایک روزن کھولتی ہے۔
طبیعیات کے قوانین سے منحرف ذرّہ
ایک انتہائی اہم تجربے میں سائنس دانوں کو یہ شواہد ملے کہ موان نامی ایٹمی ذرہ طبیعیات کے مسلمہ قوانین سے انحراف کررہا ہے۔ یہ قوانین طبیعیات کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ نظریے میں واضح کیے گئے ہیں جو ’اسٹینڈرڈ ماڈل‘ کہلاتا ہے۔
امریکی ریاست الی نوائس میں واقع فرمی نیشنل ایکسلریٹر لیبارٹی (فرمی لیب) میں کیے گئے تجربے میں سائنس دانوں نے یہ پیمائش کی یہ ذرّہ اسٹینڈرڈ ماڈل میں وضع قوانین کے تحت توقع سے زیادہ تیزرفتاری سے گردش کررہا تھا۔ سائنس دانوں کے مطابق اس تجربے کے نتائج کائنات میں کسی اور ذرّے کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو اب تک دریافت نہیں ہوا۔
چاند کی تشکیل کے مراحل کی اولین واضح شبیہہ
جولائی میں سائنس داں 400 نوری سال کے فاصلے پر واقع ستاروں کے قدرے کم عمر نظام میں ایک دھندلی طشتری کی شبیہہ حاصل کرنے میں کام یاب ہوئے۔ یہ دراصل ایک دیوقامت گیسی سیارہ تھا جس کے گرد ممکنہ طور پر اس کے چاند تشکیل پارہے تھے۔ سائنس دانوں کے مطابق یہ کسی نظام کوکب میں برفیلے چٹانی دائرے کی پہلی واضح شبیہہ تھی جو چاند کی تشکیل کے وقت نمودار ہوتا ہے۔
یہ طشتری یا ڈسک ستاروں کے جس نظام میں پائی گئی اس میں صرف دو کم عمر سیارے ہیں جن کی تشکیل 60لاکھ سال قبل ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے خلائے بسیط میں سیاروں کی تشکیل کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔
کروڑوں سال قدیم دیوقامت پرندے کے رکاز کی دریافت
2013ء میں برازیل میں پولیس نے ایک بڑی کارروائی میں اسمگلروں کے قبضے سے ہزاروں قدیم چٹانی پتھر برآمد کیے تھے جنھیں وہ ملک سے باہر اسمگل کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ ان بڑے بڑے سنگی ٹکڑوں پر معدوم حیاتیاتی انواع کے نشانات نظر آرہے تھے۔ اسی وقت سے سائنس داں ان چٹانی ٹکڑوں پر تحقیق کررہے تھے۔ گذشتہ برس محققین نے اپنی ایک تحقیق کی اشاعت میں انکشاف کیا ان سنگی ٹکڑوں میں سے ایک بڑا ٹکڑا گیارہ کروڑ سال قبل روئے زمین پر پائے جانے والے دیوقامت پرندے کا رکاز (فوسل) تھا۔ یہ پرندہ ’ٹیروسار‘ کہلاتا تھا۔ محققین کے مطابق یہ ٹیروسار کا تقریباً مکمل ڈھانچا تھا جس میں کچھ نرم بافتیں بھی موجود تھیں۔ اس دریافت پر ماہرین کا کہنا تھا کہ اس رکاز کا مل جانا کسی لاٹری سے کم نہیں۔
طویل ترین سیارچہ
ماہرین فلکیات نے گذشتہ برس جون میں تصدیق کی کہ آسمان پر دکھائی دینے والا ایک لمبا روشن نشان دراصل ایک سیارچہ ہے، جسے اب تک دیکھا جانے والا سب سے بڑا سیارچہ کہا جاسکتا ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق اس کی طوالت 93 میل ہے اور یہ سورج سے پونے تین ارب میل کے فاصلے پر ہے۔ اگلے ایک عشرے کے دوران یہ طویل ترین سیارچہ روشن تر ہوتا جائے گا کیوں کہ اس کا رُخ نظام شمسی کی جانب ہے۔ 21 جنوری 2031ء کو یہ زمین سے کم ترین فاصلے پر آجائے گا۔
https://www.express.pk/story/2271476/508/
"ہمیں خلا میں روسیوں کا پیشاب ری سائیکل کرکے پینا پڑتا ہے" امریکی خلاباز کا تہلکہ خیز انکشاف
Feb 01, 2022 | 17:35:PM

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) بین الاقوامی خلائی سٹیشن میں وقت گزارنے والے ایک امریکی خلاءباز نے ایک ایسا کراہت آمیز انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر ہی جی متلانے لگے۔ دی سن کے مطابق امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے خلاءنورد سٹیو سوانسن 2014ءمیں بین الاقوامی خلائی سٹیشن پر رہے۔ انہوں نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طرح خلائی سٹیشن پر امریکی خلاءباز، روسی خلاءبازوں کا پیشاب ’ری سائیکل‘ کرکے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
سٹیوسوانسن نے بتایا ہے کہ ”بین الاقوامی خلائی سٹیشن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ روسی خلاءبازآپریٹ کرتے ہیں جبکہ دوسرا حصہ امریکہ دیگر کئی ممالک کے ساتھ مل کر آپریٹ کرتا ہے۔ زمین پر امریکہ اور روس کے درمیان تعلق کیسے بھی رہیں، خلاءمیں یہ بقاءکا معاملہ ہوتا ہے اور ہمیں روسی خلاءبازوں کا پیشاب پینا پڑتا ہے۔ “
سٹیو نے بتایا کہ ”خلائی سٹیشن پر امریکہ اور روس کی زمین پر مخاصمت اتنی اثرانداز نہیں ہوتی۔ خلائی سٹیشن کے دونوں حصوں میں کام کرنے والے ماہرین کو اپنی اپنی بقاءکے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ جب میں خلائی سٹیشن میں تھا، اس وقت زمین پر روس کریمیا پر قبضہ کر رہا تھا اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے لیکن خلائی سٹیشن میں کوئی اس معاملے پر بات بھی نہیں کرتا تھا، وہاں ہم اس طرح اتفاق سے رہتے تھے، جیسے زمین پرایسا کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔“
https://dailypakistan.com.pk/01-Feb-2022/1397788?fbclid=IwAR3tgFsujdqpkN3PLqWcMMPWXAlv4L71o76S9fA9sGo_RvXMx8Eibj4fxwM
انسان سے بھی پہلے خلا کا سفر کرنے والا چمپنزی
Feb 01, 2022 | 17:35:PM
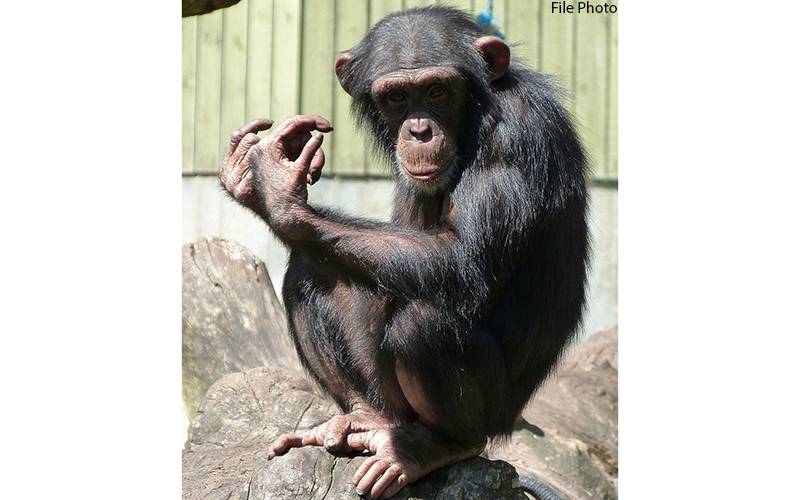
سورس: Pixabay.com (creative commons license)
نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) 31جنوری 1961ءکو تاریخ میں پہلی بار ایک چمپنزی کو خلاءمیں بھیجا گیا تھا۔ گزشتہ روز اس سائنسی کامیابی کو 61سال مکمل ہو گئے۔ ڈیلی سٹار کے مطابق اس چمپنزی کا نام ’ہیم‘ تھا جسے ’مرکری ریڈ سٹون راکٹ‘ میں بٹھا کر خلاءمیں پہنچایا گیا تھا۔ہیم کے بعد اسی سال اپریل میں سوویت یونین کے خلاءنورد یوری گاگرین خلاءمیں گئے۔
رپورٹ کے مطابق ہیم کو امریکی ریاست فلوریڈا میں کیپ کیناورل سے امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے ماہرین نے خلاءمیں بھیجا تھا۔ ہیم کی یہ فلائٹ ساڑھے 16منٹ تک رہی اور وہ157میل کی بلندی تک گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سفر میں ہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا تاہم وہ جب واپس آیا تھا تو اس کے جسم میں قدرے پانی کی کمی محسوس کی گئی۔
خلاءمیں جانے تک اس چمپنزی کا کوئی نام نہیں تھا۔ جب وہ بخیریت خلاءسے واپس زمین پر آ گیا تو اسے ’ہیم دی ایسٹرو چمپ‘ (Ham the Astrochimp)کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے امریکی ایئرفورس اور سائنسدان اسے ’نمبر 65‘ کہہ کر پکارتے تھے۔
رپورٹ کے مطابق ہیم 1957ءمیں کیمرون ، افریقہ میں پیدا ہوا تھا۔ اسے شکاری پکڑ کر فلوریڈا کے شہر میامی لائے تھے، جہاں سے اسے امریکی ایئرفورس نے خرید لیا۔ اس کے علاوہ دیگر چند چمپنزی بھی خرید کر ہولومین ایئرفورس بیس پر رکھے گئے تھے اور انہیں مسلسل ایسے ہی تجربات کی تربیت دی جاتی رہی تھی۔
https://dailypakistan.com.pk/01-Feb-2022/1397787?fbclid=IwAR2RO6Gqm-zS2BM8eVLIJ5Q-qzFdefdJLVyMkl5EMCEZiRx0zezyLGWx9Pg
چاند پر چلانے کیلئے لینڈ کروزر کی تیاری شروع، دلچسپ تفصیلات آگئیں
Feb 01, 2022 | 17:18:PM

ٹوکیو(مانیٹرنگ ڈیسک) جاپانی کارساز کمپنی ٹویوٹا نے چاند کے لیے لینڈ کروزر تیار کرنی شروع کر دی۔ ویب سائٹ ’پروپاکستانی‘ کے مطابق اس گاڑی کو ’لونر کروزر‘ کا نام دیا گیا ہے جو ٹویوٹا کمپنی جاپان کی خلائی تحقیقاتی ایجنسی کے اشتراک سے تیار کر رہی ہے۔ گاڑی کا یہ نام زمین پر دوڑنے والی ٹویوٹا لینڈ کروزر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جاپان کی سپیس ایجنسی نے یہ منصوبہ 2040ءتک انسان کے چاند پر رہنے اور پھر زندگی کو مریخ پر لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ چاند پر انسان کے قیام کے دوران یہ ’لونر کروزر‘ گاڑی چاند کی سطح پر نقل و حرکت کے لیے استعمال کی جائے گی۔
رپورٹ کے مطابق لونر کروزر رواں دہائی کے آخر میں لانچ کی جائے گی۔ ٹویوٹا موٹر کارپوریشن میں لونر کروزر پراجیکٹ کے سربراہ تاکاﺅ ساتو کاکہنا ہے کہ ”لونرکروزر اس سوچ کے ساتھ تیار کی جا رہی ہے کہ لوگ چاند کی سطح پر اس گاڑی کے اندر رہتے ہوئے ہی بحفاظت تمام کام کر سکیں، کھا، پی اور سو سکیں اور دیگر افراد کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ “ تاکاﺅ کا کہنا تھا کہ ”خلاءمیں جا کر ہم شاید ایسی جدید ترین ٹیلی کمیونیکیشنز اور دیگر ٹیکنالوجی تیار کر سکیں جو زمین پر بھی انسانی زندگی کو بہتر بنا سکے۔“
https://dailypakistan.com.pk/01-Feb-2022/1397776?fbclid=IwAR2oU-qZndoz-Tq5C8NempqZtfoj4bUHdqxTMpBPKc9NbdgtBKdm7zF1l_I
کورونا کی عالمی وبا نے پوری دنیا کو کئی مشکلات سے دوچار کردیا ہے۔ اب عالمی طور پر روزانہ لاکھوں فیس ماسک کوڑے دانوں میں پھینکے جارہے ہیں لیکن اچھی خبریہ ہے کہ اب ان سے کم خرچ اور مؤثر بیٹیریاں بنائی جاسکتی ہیں۔
2020 میں کئے گئے ایک مطالعے سے انکشاف ہوا تھا کہ کورونا وبا کے ابتدائی چند ماہ میں پوری دنیا میں 129 ارب فیس ماسک استعمال کے بعد تلف کئے گئے اوریوں زمین، فضا اور سمندروں میں ان کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔
ماسک کے اس کچرے سے تعمیراتی خام مال اور سڑک بنانے کا کام تو لیا ہے لیکن اب پہلی مرتبہ ماسک سے سستی، مؤثراور پائیدار بیٹریاں بنانے کی سنجیدہ پیشرفت ہوئی ہے۔
سب سے پہلے استعمال شدہ ماسک کو صاف اور جراثیم سے پاک کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں گرافین کی روشنائی میں ڈبویا گیا۔ اگلے مرحلے میں ماسک کو دبا کر انہیں 140 درجے سینٹی گریڈ تک گرم کیا گیا۔ پھر ان سے باریک گولیاں بنائی گئیں جو بیٹری کے برقیروں (الیکٹروڈز) کی طرح کام کرتی ہیں۔ ان کے درمیان حاجز( انسولیشن) کی پرتیں بھی لگائی گئیں اور وہ بھی پرانے ماسک سے بنائی گئی ہیں۔
اگلے مرحلے میں اس پورے نظام کو ایک الیکٹرولائٹ محلول میں ڈبوکر اس پر حفاظتی پرت چڑھائی گئی ہے اور وہ بھی طبی کچرے سے بنائی گئی تھی جن میں گولیوں کے خالی بلسٹر پیک بھی شامل ہیں۔
اگرچہ اس سے بھی اربوں ماسک صاف کرنے میں معمولی مدد ملے گی لیکن اس کے استعمال کی کوئی راہ ضرور نکلے گی۔ یہ تحقیق روس کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کی ہے اور ان کا دعویٰ ہہے کہ ماسک کی بیٹریوں سے انہوں نے 99.7 واٹ آور فی کلوگرام بجلی حاصل کی ہے جو ایک اہم کامیابی بھی ہے۔ یہ معیار لیتھیئم آئن بیٹریوں کے قریب قریب ہے جو عام استعمال ہورہی ہیں۔ لیتھیئم آئن بیٹریوں سے 100 تا 265 واٹ آور فی کلوگرام بجلی حاصل ہوسکتی ہے۔
اس میں سائنسدانوں نے کیلشیئم کوبالٹ آکسائیٹ پرووسکائٹ کے نینوذرات ملاکر اسے مزید بہتر بنایا ہے۔ اس سے انرجی ڈینسٹی ( توانائی کی کثافت) دوگنی ہوچکی ہے جو 208 واٹ آور فی کلوگرام تک ہے۔ لیکن متروکہ ماسک سے بنی بیٹریوں کو بازار تک پہنچنے میں اب بھی کئی برس لگ سکتے ہیں۔
https://www.express.pk/story/2278851/508/
ٓسٹریلیا کے سائنسدانوں نے ایک ڈجیٹل اسٹیتھواسکوپ اور سافٹ ویئر بنایا ہے جو نومولود بچے کے سینے کی آوازیں سن کر ان میں ممکنہ امراض کی پیشگوئی کرسکتا ہے۔
غریب اور دوردراز علاقوں میں اس ایجاد سے کئی بچوں کی جان بچائی جاسکتی ہے کیونکہ مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ سے چھوٹے بچوں اور نومولود اطفال میں بیماری کا بڑی حد تک درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
آئی ای ای ای ایکسپلور ڈجیٹل لائبریری میں شائع رپورٹ کے مطابق یہ ایک بہت حساس ڈجیٹل اسٹیتھواسکوپ تیار کی ہے جو پھیپھڑوں، سانس اور دل کی آواز کو بہت گہرائی میں ریکارڈ کرتی ہے۔ اس طرح بچوں میں سانس، پھیپھڑوں اور دل کے وابستہ ان گنت امراض کی شناخت ممکن ہوسکتی ہے۔
ہم پہلے ہی یہ جانتے ہیں کہ مختلف بیماریاں ہوں یا انفیکشن ، اس صورتحال میں سینے سے اٹھنے والی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ماہر ڈاکٹر اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کو محسوس کرکے ممکنہ مرض تک پہنچ جاتا ہے۔
موناش یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر فائزہ مرزبن رعد اور ان کے ساتھیوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس سے غریب ممالک کی آبادی فیضیاب ہوسکتی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ کا تعلق ایران سے ہے اور انہوں نے شیراز یونیورسٹی سے برقی انجینیئرنگ میں ماسٹرکیا اور موناش یونیورسٹی سے اسی شعبے میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ وہ ایک عرصے سے ڈجیٹل تشخیص کے نت نئے طریقوں پر غور کررہی ہیں۔ تاہم انہوں نے نومولود بچوں کو اپنی تحقیقی کا ہدف بنایا ہے۔
ڈجیٹل طریقے سے سینے اور پھیپھڑے کی آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اس آواز میں شامل شور اور اطراف کی آوازوں کو ہٹادیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سافٹ ویئربتاتا ہے کہ سینے میں سے سیٹی کی آواز آرہی ہے یا کھڑکھڑاہٹ ہے کیونکہ دونوں کا تعلق دو مختلف کیفیات سے ہوسکتا ہے۔
اس دوران سافٹ ویئر بھی مرض کی کیفیت کا اندازہ لگاتا رہتا ہے۔ والدین گھر بیٹھے بچے کے سینے اور سانس کی آوز ریکارڈ کرکے ڈاکٹر کو بھیج سکتے ہیں اور وہ انہیں سن کر بچے کا علاج یا مزید ٹیسٹ تجویز کرسکتےہیں۔
ڈاکٹر فائزہ نے بتایا کہ والدین ڈجیٹل اسٹیتھو اسکوپ کو بچے کے سینے پر لگا کر آوازیں ریکارڈ کرسکتےہیں۔ اس دوران سافٹ ویئر والدین کی مدد کرتا رہتا ہے کہ آواز ریکارڈ کرنے کے لیے اسٹیتھواسکوپ کو کس مقام پر کتنی مرتبہ رکھنا ہے۔
اپنی ایجاد کی افادیت کے لیے ڈاکٹر فائزہ اور ان کی ٹیم نے موناش چلڈرن ہسپتال کا رخ کیا اور اور 119 بچوں پر آزمائش کی جو پوری مدت یا قبل ازوقت پیدا ہوئے تھے۔ ان آوازوں کو بعد میں سافٹ ویئر سے پروسیس کیا گیا۔
بچوں کے ایک ماہر ڈاکٹر اتول ملہوترا کہتے ہیں کہ بہت چھوٹے اور قبل ازوقت پیدا ہونے والے بچوں کے سینے کی آواز محسوس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اول تو اس میں دیگر آوازیں شامل ہوتی ہیں اور دوم یہ بہت مدھم ہوتی ہیں۔ اسی لیے بار بار ان بچوں ک ایکسرے لیے جاتےہیں لیکن اب اس طریقے سے بہت آسانی سے بچوں کی سانس اور پھیپھڑوں کی آواز کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔
فی الحال اس نظام کی مزید آزمائش جاری ہے اور اس برس کے وسط تک اسے فروخت کے لیے پیش کردیا جائے گا۔
https://www.express.pk/story/2279316/9812/
دنیا بھر میں کروڑوں افراد جھلسنے اور جلنے کے بعد شدید کرب کے شکار ہوجاتےہیں اور انہیں جلد کے پیوند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی نے ایک مشینی عمل تیار کیا ہے جو انہی مریضوں کے خلیات سے حقیقت سے قریب ترجلد کی بافتیں تیار کرسکے گا۔
یہ مشین مریض کی جلد کے نمونے سے بہت تیزی سے مریض کے لیے انتہائی موافق جلد کے بڑے بڑے ٹکڑے بناتی ہے۔ اس طرح دنیا بھر میں سالانہ ایک کروڑدس لاکھ بالغ اور بالخصوص بچے فائدہ اٹھاسکیں گے جو بہت شدت سے جھلس جاتے ہیں۔
کیو یو ٹی آئی ایس ایس نامی کمپنی کی ڈینیئلہ مارینو کے مطابق نہ یہ مصںوعی جلد ہے لیکن یہ حقیقی جلد بھی نہیں بلکہ ان کے درمیان کی شے ہے۔ اسے بایو انجنیئرنگ سے تیارشدہ جلد کے قائم مقام سمجھنا چاہیے۔
اس جلد کو ڈینووواسکن کا نام دیا گیا ے جس کی موٹائی ایک ملی میٹر ہے اور یہ حقیقی جلد کے بہت قریب ہے۔ اسے بنانے کے لیے جلے ہوئے مریض کی جلد کے کیوٹینیئس خلیات لے کر انہیں تجربہ گاہ میں باقاعدہ فروغ دیا جاتا ہے ۔ اب ایک پلیٹ کے برابر جلد کا ٹکڑا بنایا جاسکتا ہے اور اسے ہائیڈروجل میں ملاکر پیش کیا جاتا ہے۔
اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سکے جتنی جلد کے ٹکڑے سے ایک پلیٹ کے برابر کھال تیار کی جاسکتی ہے۔ کئی برس پہلے یہ تجربہ گاہ کے تمام ٹیسٹ اور معیارات سے گزرچکی ہے۔ اب اس اہم ایجاد کو دوسرے طبی مرحلے پر آزمایا جارہا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین ن بھی اسے جلد کے ایک نایاب مرض کے استعمال میں منظور کرلیا ہے۔
کمپنی نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ بعض مریض تیسرے درجے تک جل جاتے ہیں۔ ان کے زخم گہرے ہوتے ہیں اور رگیں واضح ہوجاتی ہیں۔ یہاں یہ مصنوعی جلد فوری طور پر استعمال کرکے ایسے مریضوں کی جان بچاسکتی ہے۔ مشین سے تیارکردہ جلد پہلے ہی بہت سے ایسے مریضوں پر لگائی جاچکی ہے جن کے بدن کا بڑا حصہ جھلس کرتباہ ہوچکا تھا۔
لیکن اب بھی فیزتھری ٹرائل تک پہنچنے کے لیے اس کی افادیت ثابت کرنا باقی ہے۔ تاہم توقع ہے کہ تجارتی طور پر یہ 2023 تک مارکیٹ میں پیش کی جاسکے گی۔ تاہم اب بھی مصنوعی جلد کی قیمت بہت زیادہ ہے جسے کم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
https://www.express.pk/story/2279377/9812/
ہارڈ ڈسک بنانے والی مشہورِ زمانہ کمپنی ’سی گیٹ‘ نے 22 ٹیرابائٹ (22,528 گیگابائٹ) گنجائش والی ہارڈ ڈرائیو کی محدود پیمانے پر فروخت شروع کردی ہے۔
ویب سائٹ ’ٹامز ہارڈویئر‘ کے مطابق، 22 ٹیرابائٹ ہارڈ ڈرائیو کی فروخت کا آغاز صرف چند صارفین سے کیا گیا ہے تاہم یہ جلد ہی بڑے پیمانے پر فروخت کےلیے دستیاب ہوگی؛ اور اس کی قیمت کا اعلان بھی اسی وقت کیا جائے گا۔
سی گیٹ کا کہنا ہے کہ روایتی مقناطیسی ہارڈ ڈسک میں پہلے سے زیادہ ڈیٹا سمونے کےلیے ’سنگلڈ میگنیٹک ریکارڈنگ‘ (ایس ایم آر) ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔
اس طرح 20 ٹیرابائٹ والی ہارڈ ڈسک میں 22 ٹیرابائٹ ڈیٹا کامیابی سے محفوظ کیا گیا ہے۔
سرِدست بازار میں زیادہ سے زیادہ 20 ٹیرابائٹ والی ہارڈ ڈرائیوز دستیاب ہیں جو بالترتیب سی گیٹ کی ’’آئرن وولف پرو‘‘ اور ویسٹرن ڈیجیٹل کی ’’ڈبلیو ڈی گولڈ‘‘ ہیں جبکہ ان دونوں کی قیمت 600 ڈالر سے زیادہ ہے۔
لہذا یہ توقع کی جاسکتی ہے ک سی گیٹ کی 22 ٹیرابائٹ والی ہارڈ ڈرائیو بھی اچھی خاصی مہنگی ہوگی۔
واضح رہے کہ سی گیٹ کی جانب سے پہلے ہی اعلان کیا جاچکا ہے کہ وہ 2023 تک 30 ٹیرابائٹ، 2026 تک 50 ٹیرابائٹ، اور 2030 تک 100 ٹیرابائٹ گنجائش والی ہارڈ ڈسک ڈرائیوز فروخت کےلیے پیش کردے گی۔
https://www.express.pk/story/2278710/508/
چین کی ایک کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ایسے ’پروں والے راکٹ‘ پر کام کررہی ہے جو مسافروں کو لے کر صرف ایک گھنٹے میں بیجنگ سے نیویارک تک پہنچ جائے گا
یعنی یہ راکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مسافر بردار ہوائی جہاز بھی ہوگا۔
اسے چینی کمپنی ’اسپیس ٹرانسپورٹیشن‘ نے تیار کیا ہے، جس کا کہنا ہے کہ یہ راکٹ نما ہوائی جہاز (یا طیارہ نما راکٹ) مستقبل میں مسافروں کو دور دراز مقامات تک بہت کم وقت میں پہنچانے کے علاوہ مصنوعی سیارچوں اور دیگر سامان کو خلائی مدار میں چھوڑنے کا کام بھی کرسکے گا۔
اسے ایک بڑے طیارے کے نچلے حصے میں رکھ کر خاصی بلندی تک پہنچایا جائے گا جہاں یہ اس سے الگ ہوگا اور اپنا راکٹ انجن اسٹارٹ کرکے برق رفتاری سے منزلِ مقصود کی طرف پرواز کرنے لگے گا۔
اس طرح یہ 7000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے، اپنے مسافروں کو صرف ایک گھنٹے میں بیجنگ سے نیویارک تک پہنچا دے گا۔
اپے سفر کا بیشتر حصہ یہ خلا میں رہتے ہوئے طے کرے گا، اور اس طرح ضرورت پڑنے پر یہ خلائی سیاحت میں بھی کام آسکے گا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر یہ کسی راکٹ کی طرح بالکل عموداً زمین پر اترے گا۔
بتاتے چلیں کہ اس وقت خلائی سفر اور خلا میں مختلف ساز و سامان پہنچانا بہت مہنگا سودا ہے۔ یہ اخراجات کم کرنے کےلیے پچھلے کئی عشروں سے مختلف ملکوں میں ’فضائی خلائی جہاز‘ اور دوبارہ استعمال کے قابل خلائی راکٹوں جیسے درجنوں منصوبوں پر کام ہورہا ہے مگر اب تک ان میں سے کوئی ایک منصوبہ بھی قابلِ ذکر کامیابی حاصل نہیں کرسکا ہے۔
’اسپیس ٹرانسپورٹیشن‘ کی جانب سے اب تک اس منصوبے کی زیادہ تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں البتہ اس کی ویب سائٹ پر ایک اینی میشن سے مستقبل کا ایک منظرنامہ ضرور دکھایا گیا ہے۔
https://www.express.pk/story/2277820/508/
جان ہاپکنز یونیورسٹی، امریکا میں تیار کردہ روبوٹ سرجن نے دنیا میں پہلی بار مکمل خودکار طور پر چار کامیاب آپریشن کرکے سرجری کی نئی تاریخ رقم کردی ہے۔
پیٹ کے یہ تمام آپریشن تجرباتی تھے جو سؤروں پر کیے گئے۔ ان کے بعد یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ روبوٹ سرجنز جلد ہی انسانوں کے خودکار آپریشن کرنے لگیں گے۔
یہ صرف روبوٹ نہیں بلکہ روبوٹ بازو، تھری ڈی کیمروں، حساسیوں (سینسرز) اور خصوصی الگورتھم پر مشتمل ایک بھرپور نظام ہے جسے ’اسمارٹ ٹشو آٹونومس روبوٹ‘ یا مختصراً اسٹار (STAR) کا نام دیا گیا ہے۔
اسے جان ہاپکنز یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس اور مکینیکل انجینئرنگ کے اسسٹنٹ پروفیسر حامد سعیدی اور ان کے ساتھیوں نے 2016 میں تیار کیا تھا جبکہ ابتدائی طور پر اس سے ایک سؤر کا آپریشن بھی کیا گیا تھا۔
البتہ یہ مکمل خودکار آپریشن نہیں تھا بلکہ چند مرحلوں پر سرجنز کو بھی مداخلت کرنا پڑی تھی۔
تقریباً پانچ سال تک مسلسل بہتر بنانے کے بعد، اب ’اسٹار‘ اس قابل ہوگیا ہے کہ کسی بھی قسم کی انسانی مداخلت یا رہنمائی کے بغیر، مکمل خودمختار انداز میں آپریشن کا پیچیدہ عمل انجام دے سکے۔
اس میں مطلوبہ مقام پر کھال کو کاٹنے، متعلقہ اندرونی حصے کرنے اور سب سے آخر میں وہ مقام بند کرنے تک، وہ تمام مراحل شامل ہیں جو سرجری کے تحت آتے ہیں۔
’اسٹار‘ کی درستگی آزمانے کےلیے یکے بعد دیگر چار سؤروں میں چھوٹی آنت کے آپریشن کیے گئے جن کےلیے کھال پر چھوٹے سے حصے پر چیرا لگا کر آلاتِ جراحی اندر داخل کیے گئے اور مختصر سے حصے کا آپریشن کیا گیا۔
ڈاکٹر حامد سعیدی کے مطابق ’اسٹار‘ نے ’’انسان سرجنز کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر نتائج دیئے۔‘‘
نوٹ: یہ تحقیق ’سائنس روبوٹکس‘ کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہوئی ہے۔
https://www.express.pk/story/2277282/508/
امریکی انجینئروں نے ایک انتہائی حساس روبوٹ شکنجہ بنایا ہے جو انڈا توڑے اور اس کی زردی بکھیرے بغیر اسے تھام سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک باریک انسانی بال بھی اٹھاسکتا ہے۔
اسے نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی کے جائی یِن اور ان کے ساتھیوں نے تیار کیا ہے۔ یہ روبوٹ مضبوط، لچکدار اور انتہائی حساس ہے۔ ماہرین کے مطابق نرم روبوٹ اور بایومیڈیکل ٹیکنالوجی میں اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اسے جاپانی فن کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ اس قدیم فن کو کائری گامی کہا جاتا ہے۔
کائری گامی میں دو جہتی ساخت یا مٹیریئل کو اس طرح موڑا جاتا ہے کہ وہ تھری ڈی یعنی سہ رخی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ اس کے لیے خاص مٹیریئل کی یکساں پٹیاں کاٹی گئی ہیں۔ اس میں دو جہتی مٹیریئل نیچے سے گول ہوجاتا ہے اور تھری ڈی رخ اختیار کرلیتا ہے۔
اس پر کام کرنے والے ایک اور سائنسداں یاآوئے ہونگ کے مطابق اگر آپ جان لیں کہ آپ کو کس طرح کی تھری ڈی ساخت درکار ہے اور تو درست دو ابعادی مٹیریئل سے اسے بنایا جاسکتا ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کےلیے پٹیوں کو کھینچا اور سکیڑا جاتا ہے اور یوں وہ خاص شکل اختیار کرلیتا ہے۔
لیکن یہ پورا طریقہ بہت سادہ ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے۔ یہ اتنا حساس ہے کہ اس سے انسانی بال بھی اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح انسانی سرجری میں نرم روبوٹ کو لاتعداد طریقوں سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پھر انہیں ہڈیوں وغیرہ کی حرکات پر بطور پلاسٹر بھی لگایا جاسکتا ہے۔ اس طرح لاتعداد طبی استعمالات ہوسکتے ہیں۔
https://www.express.pk/story/2276604/508/
بچوں میں توجہ کی کمی دورکرنے کے عام مرض ’اے ڈی ایچ ڈی‘ کو دور کرنے والا ایک ویڈیو گیم بنایا گیا ہے جسے ’فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی‘ (ایف ڈی اے) نے منظورکرلیا ہے۔
اٹینشن ڈیفی سٹ ہائپرایکٹوو ڈس آرڈر ( اے ڈی ایچ ڈی) کی کیفیت اکثر بچوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ یہ بچے چین سے نہیں بیٹھتے، پڑھنے یا کام پر توجہ کمزور ہوجاتی ہے، اور مختلف کام نہیں کرپاتے۔ والدین کے لیے بسا اوقات سوہانِ روح بن جاتےہ ہیں۔

اب فیس بک کے سابق ایگزیکٹو چمات پالیا پتیا نے آکیلی انٹرایکٹوو کے ساتھ ملکر 2020 میں اینڈیورآر ایکس نامی گیم بنایا تھا جو بچوں میں اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تقریباً ایک ہزار ڈاکٹر نے اس گیم کو مفید پایا اب اسے ایف ڈی اے نے تجارتی پیمانے پر منظور کرلیا ہے۔
اس کے بعد بالغان کی اے ڈی ایچ ڈی دور کرنے کے لیے ایک اورگیم کی تیاری جاری ہے۔ اس کے علاوہ آٹزم کے خلاف گیم پر بر بھی غور کیا جارہا ہے۔ اینڈیور ایکس میں مختلف کارٹون کردار سامنے آتے ہیں جو 8 سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔
اس میں ایک کارٹون کردار کے ساتھ بچے کو مراحل پار کرنے ہوتے ہیں۔ اس دوران اسکرین پر تصاویر اور مختلف آوازیں توجہ بٹاتی ہیں لیکن بچہ گیم کھیل کر اگے بڑھتا رہتا ہے۔اس طرح بچے کی توجہ بہتر ہوتی ہے اور اس کا اثر عام زندگی پر بھی دکھائی دیتا ہے
https://www.express.pk/story/2277007/9812/
ایڑی کا پرانا اور شدید درد پلینٹر فیسائٹس کہلاتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ اور شدید جلن پیدا کرتا ہے جس کا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب جامعہ پٹس برگ نے ان مریضوں کے پیٹ کی چربی انجکشن میں بھر کر ان کے علاج میں جزوی کامیابی حاصل کی ہے۔
اگرچہ اس میں صرف 14 افراد پر ہی تجربات ہوئے لیکن ان کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہیں۔ دوسری صورت میں آپریشن سے کچھ آرام ملتا ہے ورنہ روز ایڑی کے نیچے بیلن یا گیند کو رکھ کر دبانے سے کچھ آرام ملتا ہے۔ لیکن چربی کے ٹیکے سے ان مریضوں کو نئی امید ملی ہے جس کی روداد جرنل آف پلاسٹک اینڈ ری کنسٹرکشن سرجری میں 25 جنوری کو شائع ہوئی ہے۔ یہاں بتانا ضروری ہے کہہ یہ کیفیت ایک مسلسل عارضہ بن جاتی ہے اور کسی بھی طرح چین نہیں ملتا۔
جامعہ پٹس برگ کے جیف گیوسنوف اور ان کے ساتھیوں کے مطابق خود مریض کی چربی ایڑی میں پہنچ کر اندر کی بافتوں کی نمو دوبارہ بڑھاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چربی میں اسٹیم سیل (خلیاتِ ساق) کے ساتھ ایسے اجزا بھی ہوتے ہیں جو حیاتیاتی اجسام کی نمو کرتے ہیں۔
14 مریضوں کے پیٹ کی بافت (ٹشو) سے چربی نکالنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا اور اس چربی کو انجکشن میں بھرا۔ بعد میں ٹیکے کو ایڑی میں لگا کر چربی کے اندر داخل کیا گیا۔ اس کے بعد چھ ہفتوں کی احتیاط کرائی گئی لیکن چھ ماہ سے ایک سال میں مریض کو بہت آرام ملا اور اکثریت نے اسے ایک انقلابی قدم قرار دیا ہے۔
ڈاکٹروں کے مطابق ٹیکہ لگانے سے فوری آرام نہیں ملتا لیکن اس کے جادوئی اثرات چھ ماہ میں ظاہر ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک مختصر مطالعہ ہے جس کے بعد مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
https://www.express.pk/story/2276470/9812/
ایک امریکی کمپنی نے ورچوئل رئیلیٹی جوتے بھی تیار کرلیے ہیں جنہیں پہن کر آپ کمپیوٹر پر تخلیق کی گئی مجازی دنیا کو اپنے پیروں میں محسوس بھی کرسکیں گے۔
یہ جوتے امریکی اسٹارٹ اپ کمپنی ’ایکٹو وی آر‘ (Ekto VR) نے ایجاد کیے ہیں جو فی الحال پروٹوٹائپ مرحلے پر ہیں۔ ان جوتوں کا تکنیکی نام تو ’ایکٹو ون سمیولیٹر بُوٹس‘ ہے لیکن انہیں صرف ’ایکٹو ون‘ بھی کہا جاتا ہے۔

یہ ہلکے پھلکے لیکن مضبوط کاربن فائبر سے تیار کیے گئے ہیں جو دیکھنے میں پیروں کو جکڑنے والے شکنجے کی طرح لگتے ہیں۔ انہیں وی آر چشمے یا ہیلمٹ اور جوائے اسٹک کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔

انہیں پہن کر ورچوئل رئیلیٹی کی دنیا میں چلنے پھرنے کےلیے آپ حقیقت میں اپنے پیروں کو حرکت دیتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں۔
اس طرح آپ اپنے آس پاس رکھی ہوئی چیزوں سے ٹکرائے بغیر ہی ورچوئل دنیا کی سیر کرسکتے ہیں اور بھرپور انداز سے وی آر گیمز بھی کھیل سکتے ہیں۔

پہننے والے کو ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے ’چلنے پھرنے‘ کے قابل بنانے کےلیے ان جوتوں میں چھوٹے چھوٹے پہیے لگائے گئے ہیں جو موٹروں کے ذریعے گھومتے ہیں۔
یہ وی آر چشمے اور متعلقہ کمپیوٹر سے رابطے میں رہتے ہوئے یہ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ انہیں پہننے والا (ورچوئل دنیا میں) کس سمت میں اپنے پیروں کو حرکت دے رہا ہے۔

اسی حساب سے یہ مخالف سمت میں گھوم جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پہننے والا شخص اصل میں اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے لیکن یہ بات وہ محسوس نہیں کر پاتا اور ورچوئل دنیا میں پوری آزادی سے گھومتا پھرتا ہے۔

اگر یہ جوتے پہنے ہوئے کسی شخص کو اصل میں دیکھا جائے تو یوں لگے گا کہ جیسے وہ مائیکل جیکسن کی طرح سے ’مون واک‘ کر رہا ہے… یعنی اپنے پیر ضرور آگے بڑھاتا ہے لیکن کھسک کر واپس اسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے اس نے ’چلنا‘ شروع کیا تھا۔
وی آر جوتوں کا یہ پروٹوٹائپ دیکھنے میں کچھ خاص پرکشش تو نہیں لیکن آنے والے برسوں میں یہ ’میٹاورس‘ کو حقیقت کا روپ دینے میں اہم کردار ضرور ادا کرسکتا ہے۔
دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کی میٹاورس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ امید بھی کی جاسکتی ہے کہ بہت جلد ’میٹا‘ (سابقہ فیس بُک) یا کوئی اور ادارہ اس ٹیکنالوجی کو خرید لے گا۔
https://www.express.pk/story/2276260/508/
شاخ گوبھی (بروکولی) اب پاکستان میں بھی دستیاب ہے۔ اب جاپانی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اس سپرسبزی کے اندرکینسر ختم کرنے والے طاقتور اجزا موجود ہیں۔ اس طرح یہ دوا کے علاوہ غذا بھی ہے اور مستقبل میں بروکولی یا اس کے اجزا کسی ضدِ سرطان دوا کے لیے بہترین امیدوار بھی ثابت ہوسکتے ہیں۔
پبلک لائبریری آف سائنس (پی ایل او ایس) ون میں ہیروشیما یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے خمیر(فشن ییسٹ) پر گوبھی کا اہم کیمیکل ڈی آئی ایم یعنی 3,3′-Diindolylmethane آزمایا ہے۔ یہ قدرتی مرکب خلئے (سیل) کی زندگی مکمل ہونے پر اسے ختم کرتا ہے اور پیچیدہ طریقے سے اس کی باقیات کو ری سائیکل بھی کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کینسر میں خلیات اپنی مدت پوری کرکے ختم نہیں ہوتے اور رسولیوں میں ڈھلتے رہتے ہیں جنہیں ہم کینسر ٹیومر کہتےہیں۔ تاہم خمیر کے بعد انسانوں پر ڈی آئی ایم کی آزمائش ابھی باقی ہے۔
قصہ مختصر کہ شاخ گوبھی میں پایا جانے والا ڈی آئی ایم کیمیکل سرطانی خلیات بننے سے روکتا ہے اور ایک دوا کی امید ثابت ہوسکتا ہے۔ اس سے قبل جرمنی کے ماہرین نے بتایا تھا کہ ڈی آئی ایم سادہ جانداروں کی زندگی طویل کرسکتا ہے اور یوں اس میں طویل العمری کے خواص بھی پائے جاتے ہیں۔
https://www.express.pk/story/2275500/9812/
سائنس دانوں نے سانس لینے کے عمل اور نیند کے درمیان گہرا تعلق دریافت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عملِ تنفس ہی سوتے ہوئے دماغ کا ایک اہم گھڑیال ہوتا ہے۔
ایک جانب تو سونے کا عمل محض بے حرکت ہونا نہیں ہوتا بلکہ اس میں دماغ کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں اور انہیں منظم کرنے میں سانس لینے کا عمل نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔
نیند میں دماغ بند نہیں ہوتا بس دن کے اہم معاملات اور یادوں کو ’محفوظ‘ بناتارہتا ہے۔ اس کےلیے دماغ کے بعض حصوں اور معلومات کے درمیان رابطہ رہتا ہے لیکن اس عمل کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا تھا۔
اب لڈ وِگ میکسی میلیان یونیورسٹی، جرمنی کے پروفیسر اینٹن اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ سانس کا اتار چڑھاؤ ایک طرح کا پیس میکر بنتے ہوئے دماغ کے مختلف حصوں تک پہنچتا ہے اور انہیں باہم ہم آہنگ کرتا ہے۔ عملِ تنفس ایک مستقل اور باقاعدہ نظام کی طرح کام کرتے ہوئے پورے اعصابی نظام کو خودکار بناتا ہے۔
اس کے لیے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں چوہوں کے دماغ میں برقیرے لگا کر ہزاروں نیورون کی سرگرمی کو نوٹ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انہیں باقاعدہ رکھنے میں سانس کا اتار چڑھاؤ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اہم دماغی حصوں مثلاً ہیپوکیمپس، میڈیئل پری فرنٹل اور وژول کارٹیکس سب پر ہی تنفس کا اثر ہوتا ہے۔
اس طرح معلوم ہوا کہ دماغ کے لمبک سرکٹ پر سانس لینے کا اثر ہوتا ہے۔ چونکہ ییپوکیپمس یادداشت کا گڑھ ہوتا ہے اور سانس کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملِ تنفس کی ہم آہنگی خود یادداشت اور دماغی روابط میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔
https://www.express.pk/story/2275533/9812/
ناسا نے طویل خلائی سفر پر جانے والے خلانوردوں کے لیے توانائی بھرے اور ماحول دوست کھانے کی مستقل فراہم پر ٹیکنالوجی وضع کرنے کے اعلان کرتے ہوئے اس پر دس لاکھ ڈالر انعام یا فنڈنگ کا وعدہ کیا ہے۔
اس مقابلے میں عام افراد بھی شامل ہوسکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ کھانا توانائی بھرا، لذیذ اور باکفایت ہو اور اس میں توانائی اور ماحول کا بطورِ خاص خیال رکھا جائے کیونکہ خلا میں پکوان کے لیے زمین جیسی سہولیات موجود نہیں ہوتیں۔
یہ پروگرام کینڈا کی خلائی ایجنسی کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے جس میں سائنسدانوں سے لے کر عام افراد سے بھی مدد مانگی گئی ہے۔ مقابلے کا نام ’ڈیب اسپیس فوڈ چیلنج‘ رکھا گیا ہے۔ اس میں افراد یا ٹیموں سے غذائی تیاری کی ٹیکنالوجی کی ڈیزائننگ، تیاری اور انہیں فراہم کرنے کے عملی نمونوں کا تقاضہ کیا گیا ہے۔
شرط یہ ہے کہ خلا کے اجنبی ماحول میں سائنسدانوں کو وہ تمام ضروری اجزا فراہم کیے جائیں جو غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ لیکن ناسا کے اندرونی حلقوں کے مطابق یہی ٹیکنالوجی زمین پر آفات اور قحط وغیرہ کی صورت میں غذائی ضروریات پوری کرسکے گی اور یوں اس ٹیکنالوجی کے امکانات بہت وسیع ہوسکتے ہیں۔
ناسا کے نائب ایڈمنسٹریٹر، جِم روئٹر نے بتایا کہ خلائی سفر میں خوراک پر اختراعاتی فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ٹیکنالوجی کو مستقبل کی غذا قرار دے رہے ہیں۔ اب اس کا فیز ٹو شروع ہوچکا ہے۔ اکتوبر 2021ء کے فیز ون میں 18 ٹیموں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ اس پر کچھ رقم دی گئی تھی۔
اب دوسرے مرحلے میں 10 ٹیموں کا انتخاب کیا گیا ہے اور ان کے درمیان مقابلہ جاری ہے لیکن اس دوسرے مرحلے میں امریکا سے مزید نئی ٹیمیں بھی شامل ہوسکتی ہیں اور اس بار رقم بڑھا کر ایک ملین ڈالر کردی گئی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایک مؤثر اور مکمل ٹیکنالوجی بنائی جائے تو طویل خلائی سفر میں انسانوں کا پیٹ بھرسکے۔
https://www.express.pk/story/2275164/508/
چند ماہ قبل اپنا نام ’فیس بُک‘ سے تبدیل کرکے ’میٹا‘ بننے والی کمپنی نے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کےلیے ایک خاص اور طاقتور سپر کمپیوٹر تیار کرلیا ہے جو اپنے ابتدائی مرحلے پر ہی دنیا کے تیز رفتار سپر کمپیوٹروں میں شمار ہونے لگا ہے۔ اس سپر کمپیوٹر کو ’اے آئی ریسرچ سپر کلسٹر‘ (AI RSC) کا نام دیا گیا ہے۔
اس سپرکمپیوٹر کی رفتار کتنی ہے؟ اس بارے میں ’فیس بُک اے آئی‘ پر متعلقہ بلاگ میں تو کچھ نہیں بتایا گیا ہے البتہ اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ یہ این ویڈیا کمپنی کے 6,080 جدید ترین ’اے 100 جی پی یوز‘ کو آپس میں مربوط کرکے تیار کیا گیا ہے۔
آئندہ چند ماہ کے دوران اس میں مزید 10,000 جی پی یوز کا اضافہ کیا جائے گا جس کے بعد یہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں دنیا کا طاقتور ترین سپر کمپیوٹر بھی بن جائے گا۔
اپنی موجودہ حالت میں بھی یہ کسی سے کم نہیں کیونکہ اپنے ’کوانٹم انفنی بینڈ‘ نیٹ ورک کی بدولت یہ 200 گیگابٹس فی سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا منتقل کرسکتا ہے۔
یادداشت کی بات کریں تو اس میں 175 پی-ٹا بائٹس (175,000 ٹیرا بائٹس) جتنا ڈیٹا محفوظ کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کی کیشے 46 پی-ٹا بائٹس جبکہ ’نیٹ ورک فائل سسٹم‘ (این ایف ایس) کے تحت یہ مزید 10 پی-ٹا بائٹس جتنا ڈیٹا محفوظ کرسکتا ہے۔
’اے آئی آر ایس سی‘ نے حالیہ آزمائشوں کے دوران فطری زبان (نیچرل لینگویج) سے متعلق ماڈلز کو کمپنی کے سابقہ سپر کمپیوٹرز کے مقابلے میں تین گنا تیز رفتاری سے تربیت دی، جبکہ ارد گرد کا منظر دیکھ کر ’سمجھنے‘ میں اس نے 20 گنا تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا۔
بے حد وسیع ڈیٹا (بِگ ڈیٹا) پر اپنی کمپیوٹنگ کی غیرمعمولی طاقت استعمال کرتے ہوئے یہ تصاویر اور مناظر میں موجود چیزیں پہچاننے، بات چیت میں مخصوص الفاظ شناخت کرنے، ایک سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے، اور سوشل میڈیا پر جھوٹی معلومات اور نفرت انگیز مواد کی نشاندہی کرنے والے الگورتھمز کی تیز رفتار تربیت جیسے کام بھی بخوبی کرسکے گا
بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اور اس طرح کے دیگر سپر کمپیوٹرز ’میٹاورس‘ کےلیے بھی استعمال ہوں گے جس کی خاطر فیس بُک نے اپنا نام ہی تبدیل کرکے ’میٹا‘ کرلیا ہے۔ البتہ فی الحال یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے۔
https://www.express.pk/story/2275705/508/
سائنسدانوں نے ایک وسیع انفراریڈ سینسر کو اتنا مختصر کردیا ہے جو اسمارٹ فون میں لگاکر صنعتی، غذائی اور زرعی جانچ کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
نیچرکمیونکیشن میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق اسے بنانا بہت آسان ہے جو پلاسٹک اور دودھ وغیرہ میں کیمیائی اجزا کی فوری شناخت کرلیتا ہے۔
ہماری آنکھ کے خلیات ہمیں غذا کے بارے میں خوب احساس دیتےہیں۔ اسٹرابری کا سرخ رنگ بتاتا ہے کہ یہ کھانے کے لیے تیار ہے جبکہ سبز اسٹرابری کچی ہوتی ہے۔ لیکن انسانی آنکھ کی اپنی حدود ہیں اور ہم بالائے بنفشی (الٹراوائلٹ) یا زیریں سرخ (انفراریڈ) نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم یہ روشنیاں دیکھ سکیں تو ہم بہت سے آلودگیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔
آئنڈہوون یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کی طالبہ کیلی ہیکل اور ان کے ساتھیوں نے یہ جدید سینسر بنایا ہے جو عام فون میں سماسکتا ہے۔ اسے مینٹس شرمپ نامی سمندری جانور کی آنکھ سے متاثر ہوکر تیار کیا گیا ہے جو فوری طور پر انفراریڈ اور دیگر ایسی روشنیوں کو دکھاتا ہے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔
یہ سینسر بہت جدید، تیاری میں آسان اور انتہائی کم قیمت کا حامل بھی ہے۔ لیکن اس پر مسلسل کئی برس سے تحقیق جاری تھی۔ اس کی تیاری ’مینٹی اسپیکٹرا‘ نامی اسٹارٹ اپ نے کی ہے۔ روایتی اسپیکٹرومیٹر کے مقابلے میں یہ بہت مؤثر انداز میں دودھ میں آلودگی اور چکنائیوں کا سراغ لگاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کے پلاسٹک کی شناخت بھی کرسکتا ہے۔
مینٹی اسپیکٹرا کو زراعت، پروسیس کنٹرول یا پھر دیگر امور میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اس سے پھلوں کے پکنے اور غذائیت کا احساس کیا جاسکتا ہے۔ سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے بہت آسانی سے ایک اسمارٹ فون میں رکھا جاسکتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2275095/508/
چینی انجینئروں نے دنیا کا سب سے بڑا چوپایہ روبوٹ تیار کرلیا ہے جسے انہوں نے ’مکینیکل یاک‘ (روبوٹ بیل) کا نام دیا ہے۔
چین سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار ’گلوبل ٹائمز‘ اور چینی سرکاری ٹی وی کے مطابق، یہ روبوٹ فوجی مقاصد کےلیے تیار کیا گیا ہے جو ایسے دشوار گزار اور خطرناک علاقوں میں دشمن کی نگرانی کرسکے گا جہاں پہنچنا اور پہرہ دینا فوجیوں کےلیے جان جوکھم میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔
خبروں میں اس روبوٹ کے وزن سے متعلق تو نہیں بتایا گیا لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ اس کی اونچائی ایک عام انسان کے مقابلے میں نصف ہے جبکہ لمبائی تقریباً انسان جتنی ہے۔
یہ چار پیروں پر آگے اور پیچھے چلنے کے علاوہ دائیں بائیں بھی گھوم سکتا ہے اور اپنا رُخ بدل سکتا ہے۔
یہ خود پر 160 کلوگرام وزنی سامان لاد کر 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے؛ یعنی اس کا ایک مقصد دشوار گزار علاقوں میں فوجی سامانِ رسد پہنچانا بھی ہوگا۔
’مکینیکل یاک‘ کے بارے میں چینی میڈیا کی جانب سے ٹوئٹر پر بھی ایک مختصر ویڈیو رکھی گئی ہے:
اس ویڈیو میں یہ امریکی کمپنی ’بوسٹن ڈائنامکس‘ کے تیار کردہ روبوٹ کتے ’بِگ ڈاگ‘ جیسا دکھائی دے رہا ہے تاہم چین نے وضاحت کی ہے کہ ’مکینیکل یاک‘ مقامی مہارت استعمال کرتے ہوئے ’آزادانہ طور پر‘ بنایا گیا ہے۔
یہ مصنوعی ذہانت والے سافٹ ویئر کے علاوہ کئی طرح کے حساسیوں (سینسرز) سے بھی لیس ہے جبکہ بدلتے ماحول اور حالات میں لڑکھڑائے بغیر چلتے رہنے کےلیے اس میں جوڑوں کے 12 ماڈیول بھی نصب ہیں جو اس کی حرکت کو ہموار رکھتے ہیں۔
اپنی انہی صلاحیتوں کی بدولت یہ روبوٹ ناہموار چٹانوں، سیڑھیوں، کیچڑ سے بھرے راستوں، ریگستانوں اور برف سے لدے میدانوں تک میں آسانی سے دوڑ سکتا ہے جبکہ فوجیوں کےلیے غذا اور اسلحہ لے جانے کے علاوہ، انسانوں کےلیے ناقابلِ برداشت ماحول میں نگرانی جیسے کام بھی کرسکتا ہے۔
چینی سرکاری ٹی وی کے مطابق، چین میں اسی طرح کا ایک اور منصوبہ ’گیڈا‘ (Geda) کے نام سے جاری ہے جس میں کتوں جیسے چوپایہ روبوٹ بنائے گئے ہیں۔ ایسا ہر روبوٹ صرف 32 کلوگرام وزنی ہے لیکن 40 کلوگرام تک سامان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔
’گیڈا‘ روبوٹس کو اس قابل بھی بنایا گیا ہے کہ صوتی احکامات سمجھ کر، ان پر خودکار انداز میں عمل بھی کرسکیں۔
اندازہ ہے کہ ’مکینیکل یاک‘ میں بھی یہی ٹیکنالوجی مزید بہتر کرکے استعمال کی گئی ہے۔
مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ چین 2025 تک روبوٹکس کے میدان میں ساری دنیا بالخصوص امریکا پر سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے؛ اور اس طرح کے منصوبے انہی کوششوں کا تسلسل ہیں۔
https://www.express.pk/story/2274439/508/
آنکھیں جسم کی کھڑکیاں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی جسمانی کیفیات بھی بتاسکتی ہیں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ آنکھوں کے تفصیلی معائنے سے نہ صرف درست حیاتیاتی (بائیلوجیکل) عمر معلوم کی جاسکتی ہے بلکہ قبل ازوقت موت کا اندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے۔
عمرگزرنے کے ساتھ ہی بیماریاں اور جسمانی تبدیلیاں آگھیرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عین یکساں عمر والے دو افراد میں بھی یہ یہ کیفیات مختلف ہوسکتی ہیں۔ اس طرح ماہ وسال کی بجائے اگردرست جسمانی حیات معلوم کی جائے تو وہ اصل عمر سے زائد ہوسکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماریاں اور جسمانی تبدیلیاں اصل عمر سے بڑھ کربھی ہوسکتی ہیں۔
یعنی اگر کسی شخص کو 40 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑا اور قلب کو نقصان پہنچا ہے تو اب دل کی عمر اصل عمر سے زیادہ ہوسکتی ہے کیونکہ مرض نے دل کو مزید بوڑھا کردیا ہے۔ جسم میں بعض کیمیکل، بایومارکر، جینیاتی کیفیات، دماغی صلاحیت، امنیاتی نظام اور بلڈ پریشر سے بھی بدن کی حیاتیاتی عمر معلوم کی جاسکتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ کیفیات کس قدر جان لیوا بھی ہوسکتی ہیں۔
برٹش جرنل آف اوپتھیلمولوجی میں شائع رپورٹ میں سائنسدانوں نے 40 سے 69 سال تک کے47 ہزار افراد کی آنکھوں میں پچھلے گہرے ترین حصے ’فیونڈس‘ کی 80 ہزار تصاویر لی ہیں۔ ان تمام تصاویر کو مشین لرننگ الگورتھم سے گزارا گیا جس سے مزید انکشاف سامنے آئے۔
اس سافٹ ویئر نے اصل عمر کے مقابلے میں ریٹینا کی حیاتیاتی عمر کا درست اندازہ پیش کیا۔ 51 فیصد افراد کے ریٹینا کی عمر کا فرق 3 سال، 28 فیصد کا 5 سال اور چار فیصد افراد میں 10 برس کا فرق سامنے آیا ۔ یوں ان سارے لوگوں کی آنکھوں کی حیاتیاتی عمر خود ان کی عمر سے زائد تھی۔
ان میں سے بڑی عمر کے 49 تا 67 فیصد افراد دل یا کینسر کے امراض سے ہٹ کر بھی قبل ازوقت موت کے دہانے پر تھے۔ یعنی آنکھو کا بڑھاپا موت کے خطرے کو دو سے تین فیصد تک بڑھا سکتا ہے اور اس کی ایک طرح سے پیشگوی بھی کی جاسکتی ہے۔ تاہم اب ماہرین اس کی دیگر وجوہ معلوم کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
تاہم ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آنکھیں بدن کا روزن ہوتی ہیں اور ان سے بہت ساری طبی کیفیات معلوم کی جاسکتی ہیں۔
https://www.express.pk/story/2274282/9812/
اطالوی اور برطانوی ماہرین کی ایک مشترکہ ٹیم نے اندازہ لگایا ہے کہ ہماری قابلِ مشاہدہ کائنات میں ایسے 40 ارب ارب (یعنی 40,000,000,000,000,000,000) بلیک ہولز موجود ہیں جن کی کمیت ہمارے سورج کے مقابلے میں پانچ سے 10 گنا زیادہ ہے۔
اس طرح کے بلیک ہولز کو فلکیات کی زبان میں ’اسٹیلر بلیک ہولز‘ یعنی ’ستاروں سے بننے والے بلیک ہولز‘ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورج سے کئی گنا بڑے ستاروں کے ’مرنے‘ سے وجود میں آتے ہیں۔
بظاہر سادہ اور آسان نظر آنے والا یہ تخمینہ کائنات سے متعلق جدید ترین سائنسی نظریات، کئی عشروں پر پھیلے ہوئے فلکیاتی مشاہدات، اور ’بگ ڈیٹا‘ کے طاقتور ٹولز استعمال کرتے ہوئے لگایا گیا ہے جس میں ماہرین کو کئی سال لگ گئے۔
واضح رہے کہ یہ تخمینہ دسمبر 2020 میں پیش کیا گیا تھا لیکن تب اسے پری پرنٹ سرور ’آرکائیو ڈاٹ آرگ‘ پر شائع کرکے ’ایسٹرو فزیکل جرنل‘ میں اشاعت کےلیے بھیج دیا گیا تھا۔
ایک سال کی محتاط نظرِ ثانی اور تنقید کے بعد اب یہ ریسرچ پیپر ’ایسٹرو فزیکل جرنل‘ کے تازہ شمارے میں آن لائن بھی شائع کردیا گیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہماری قابلِ مشاہدہ کائنات کو کسی بہت بڑے گولے سے تشبیہ دی جائے تو اس گولے کا قطر لگ بھگ 90 ارب نوری سال ہوگا۔
اس لحاظ سے ہماری پوری (قابلِ مشاہدہ) کائنات کا حجم 381,704 نوری سال بنتا ہے جس کے ہر ایک ارب نوری سال میں تقریباً 105 کھرب بلیک ہولز موجود ہوسکتے ہیں۔
اسی طرح اگر پوری کائنات میں کہکشاؤں کی مجموعی تعداد کے تازہ ترین تخمینے (2,000 ارب کہکشاؤں) کو بنیاد بنایا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر کہکشاں میں دو کروڑ کے لگ بھگ ایسے بلیک ہولز ہوں گے جو دیوقامت ستاروں کے خاتمے سے بنے ہوں گے۔
یاد رہے کہ ان میں وہ عظیم و جسمیم ’سپر میسیو بلیک ہولز‘ شامل نہیں جن میں سے ہر ایک کی کمیت ہمارے سورج سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ ہوتی ہے؛ اور جو ہماری ملکی وے کہکشاں سمیت، بیشتر کہکشاؤں کے عین مرکز میں پائے جاتے ہیں۔
اپنی ارد گرد زبردست سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں ’کہکشاؤں کے سرگرم مرکزے‘ (ایکٹیو گیلیکٹک نیوکلیائی) یا مختصراً صرف ’اے جی این‘ (AGN) بھی کہا جاتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2273677/508/
اٹلی کے ایک ادارے نے ’آئی کب‘ (iCub) کے نام سے ایک روبوٹ تیار کرلیا ہے جو مشہور سپر ہیرو ’آئرن مین‘ کی طرح اُڑ سکتا ہے اور امدادی کارروائیوں میں بھی ہمارے کام آسکتا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، یہ ایجاد جینوآ میں واقع ’آئی آئی ٹی‘ (اٹالین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی) کے انجینئروں نے 15 سال محنت کے بعد کی ہے؛ البتہ فی الحال یہ پروٹوٹائپ مرحلے پر ہے۔

صرف 3.4 فٹ اونچائی والے، ہلکے پھلکے ’آئی کب‘ کے دونوں بازوؤں میں چھوٹے چھوٹے جیٹ انجن نصب ہیں جو اسے ضرورت پڑنے پر اُڑان بھرنے اور اپنے مطلوبہ مقام کی سمت تیزی سے پرواز کرنے کے قابل بناتے ہیں۔

خصوصی الگورتھم کے ذریعے ’آئی کب‘ کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ اُڑان بھرنے سے لے کر زمین پر اُترنے تک، تمام مراحل میں مکمل طور پر متوازن رہے۔
اس کا چہرہ کسی بچے کی طرح دکھائی دیتا ہے جبکہ یہ چاروں ہاتھ پاؤں کے علاوہ دو پیروں پر چلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔
’آئی کب‘ کے ہاتھ مضبوط ہیں جن پر نرم مادّے کی تہہ چڑھا کر ہتھیلیاں بنائی گئی ہیں تاکہ جب یہ کوئی چیز پکڑے تو اس کے ہاتھوں کی طاقت سے وہ ٹوٹ نہ جائے۔

کسی حادثے کے بعد ملبے میں دبے ہوئے افراد کو تلاش کرنے کےلیے یہ حساسیوں (سینسرز) سے بھی لیس ہے جو خاصی گہرائی میں موجود کسی شخص کا پتا لگا سکتے ہیں۔
اپنی مختصر جسامت کی وجہ سے یہ ان مقامات تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پہنچنا امدادی کارکنوں اور ڈرونز کےلیے بے حد مشکل ہوتا ہے۔
اس کی آنکھوں میں طاقتور کیمرے بھی نصب ہیں جن کی مدد سے یہ بہت دُور کا منظر تک صاف دیکھ سکتا ہے۔
کارروائی کے دوران یہ اپنے آپریٹر سے مسلسل ریڈیائی رابطے میں رہتا ہے جو اس کی تمام پیش رفت پر نظر رکھتا ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی سمت اور رفتار وغیرہ میں تبدیلی کی جاسکے یا اسے واپس بھی بلایا جاسکے۔

ہاتھوں کے علاوہ اس کے پورے جسم پر بھی ’کھال‘ منڈھی گئی ہے جو مختلف طریقوں سے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرسکتی ہے۔
’آئی کیوب‘ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آئی آئی ٹی کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر سال تقریباً 300 قدرتی حادثات و سانحات ہوتے ہیں جو 90 ہزار انسانی جانیں لینے کے علاوہ 16 کروڑ افراد کو متاثر کرتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے بھی روبوٹکس کے شعبے کو ترقی دینا اشد ضروری ہے۔
https://www.express.pk/story/2273210/508/
شدید سردی اور برف میں کام کرنے والے افراد، مہم جو اور سپاہیوں کو ایک ہی خطرہ لاحق رہتا ہے: فراسٹ بائٹ یا برف گزیدگی؛ جس میں ناقابلِ برداشت سردی سے متاثرہ جسمانی اعضا گل سڑ کر تباہ ہوجاتے ہیں جنہیں کاٹنا پڑ جاتا ہے اور متاثرہ شخص ساری زندگی کےلیے معذور ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب ایک خاص کریم انہیں فراسٹ بائٹ کے حملے اور اعضا کی بریدگی سے بچاسکتی ہے۔
واضح رہے کہ فراسٹ بائٹ میں جلد کے اندر برف جاکر کرسٹلز (قلموں) کی شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ پیرسن ہوتے ہیں، پھرحس ختم ہوجاتی ہے اور جلد سیاہ پڑجاتی ہے۔ اس کی شدید کیفیت میں اعضا کو کاٹنا پڑجاتا ہے۔
امریکی کیمیکل سوسائٹی کے تحت ’اپلائیڈ بایومیٹیریلز‘ جرنل میں شائع شدہ ایک رپورٹ میں بھارت میں انسٹی ٹیوٹ آف جینومکس اینڈ انٹی گریٹوو بائیلوجی کی ڈاکٹر منیا گنگولی کی تیارکردہ اس کریم کی روداد شائع ہوئی ہے۔ منیا اور ان کے ساتھیوں نے خلیات کو منجمد (فریز) کرنے والے کیمیائی اجزا اور خلیات کے اندر برفیلے کرسٹل بننے سے روکنے والے ڈائی میتھائل سلفوکسائیڈ (ڈی ایم ایس او) کو باہم ملایا ہے۔ اس میں پولی وینائل الکحل (پی وی اے) ملائی گئی ہے جو خلیات کے درمیان برف جمنے روکتی ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک مؤثرمرہم بنایا ہے۔
اب باری باری ڈی ایم ایس او اور پی وی اے کی مختلف مقداروں کو زندہ خلیات پرآزمایا گیا۔ تجربہ گاہ میں یہ سب خلیات سرد ماحول میں رکھے گئے تھے اور کریم سے انہیں منجمد ہونے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ معلوم ہوا کہ اگر ڈی ایم ایس او کی دو فیصد مقدار کو 1.6 ملی گرام فی ملی لیٹر پی وی اے سے ملایا جائے تو اس کے بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یعنی اس ترکیب سے خلیات کو 80 فیصد کامیابی سے برف بننے اور تباہ ہونے سے بچالیا گیا۔
اس مرہم سے جلد کی سطح اور دیگر حصے بھی فریز ہونے سے بچ گئے۔ اب مرہم کو سِن اے ایف پی کا نام دیا گیا۔ اگلے مرحلے میں اسے ایلوویرا (گھیکوار) کی جیلی میں ملا کر ایک چوہے پر ملا گیا۔ پندرہ منٹ بعد چوہے کو انتہائی سرد ماحول میں رکھا گیا۔ حیرت انگیز طور پر چوہا سردی کے وار سے محفوظ رہا اور اس کے خلیات بھی برقرار رہے۔
پھر ایک اور چوہے میں 30 منٹ یا اس سے قبل کریم لگائی گئی اور اسے بھی انتہائی سرد ماحول میں رکھا گیا لیکن مرہم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور چوہے کے اعضا برف سے شدید متاثر ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 15 منٹ قبل کریم لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
اب اس اینٹی فراسٹ بائٹ کریم کو تجارتی پیمانے پر تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس تحقیق کی فنڈنگ امریکی ڈیفینس اینڈ ریسرچ پراجیکٹ ایجنسی (ڈارپا) نے کی تھی۔
https://www.express.pk/story/2273435/9812/
کیمبرج، میساچیوسٹس: جدید جنگی ہتھیار بنانے والی امریکی کمپنی ’ریتھیون‘ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایسی ٹیکنالوجی وضع کرلی ہے جسے استعمال کرتے ہوئے صرف ایک آپریٹر 130 ڈرونز کنٹرول کرسکتا ہے۔
یہ ٹیکنالوجی امریکی ایجنسی ’ڈارپا‘ کے ’آفسیٹ پروگرام‘ کےلیے تیار کی گئی ہے تاکہ مستقبل کے میدانِ جنگ میں کم فوجیوں کی مدد سے زیادہ تعداد میں خودکار طیارے کنٹرول کیے جاسکیں اور دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جاسکے۔
واضح رہے کہ آج کل مختلف نمائشوں میں سیکڑوں ڈرونز کی ایک ساتھ اور ہم آہنگ پرواز کے ذریعے دیکھنے والوں کی تفریح کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی عوام کی تفریح سے کہیں بڑھ کر ہے۔
عسکری ماہرین کی پیش گوئی ہے کہ آنے والے برسوں میں لڑاکا طیاروں کے علاوہ خودکار جہاز اور ڈرونز بھی افواج کا باقاعدہ حصہ ہوں گے جنہیں دور بیٹھے ہوئے آپریٹرز کنٹرول کیا کریں گے۔
یعنی مستقبل کی جنگیں صرف فوجیوں کے نہیں بلکہ ڈرونز اور خودکار جہازوں کے درمیان بھی لڑی جائیں گی۔
ریتھیون کی ٹیکنالوجی بھی ایسی ہی امریکی کوششوں کا تسلسل ہے جس کے تحت ایک آپریٹر نے 130 ڈرونز کو بیک وقت کنٹرول کرنے کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔
بڑی تعداد میں ڈرونز کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کےلیے مصنوعی ذہانت کے تحت ’’سوارم انٹیلی جنس‘‘ نامی شعبے سے استفادہ کیا گیا ہے۔
ریتھیون کے مطابق، اس ٹیکنالوجی میں سادہ سینسرز کے علاوہ کم طاقت والے مائیکرو پروسیسرز بھی استعمال کیے گئے ہیں جو اسے کم خرچ کے علاوہ آسان بھی بناتے ہیں۔
اگرچہ حالیہ تجربات میں ریتھیون نے ہوا میں اُڑنے والے 130 ڈرونز کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کا مظاہرہ کیا ہے تاہم مستقبل میں یہی ٹیکنالوجی زمین پر چلنے والی خودکار گاڑیوں اور سمندر میں تیرتی ہوئی خودکار کشتیوں اور آبدوزوں کی بڑی تعداد کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کے قابل بنا لی جائے گی۔
اس ٹیکنالوجی کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک عام فوجی بھی تھوڑی سی تربیت کے بعد اس میں مہارت حاصل کرسکتا ہے۔
کیا آنے والے برسوں میں ایک آپریٹر ایک ہزار ڈرونز کنٹرول کرسکے گا؟ اس سوال کے جواب میں ریتھیون کا کہنا ہے کہ اس پہلو پر بھی کام جاری ہے اور کچھ تحقیق کے بعد یہ بھی ممکن بنا لیا جائے گا۔
فوجیوں کو میدانِ جنگ کے منظر سے بہتر طور پر آگاہ رکھنے کےلیے ورچوئل رئیلیٹی (وی آر) چشمے بھی تیار کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اہداف پر بخوبی نظر رکھ سکیں اور دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں۔
https://www.express.pk/story/2272829/508/
اوٹاوا: خلا میں انسانی جسم کا سب سے اہم پہلو شدید متاثر ہوتا ہے اور وہ ہے ہمارا خون جو شدید متاثر ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ صرف چھ ماہ خلا میں رہنے سے خون کے 54 فیصد سرخ خلیات کو تباہ ہوسکتےہیں۔
اگرچہ اس سے قبل بھی انسان نے خلا کی بے وزنی میں مہینوں بلکہ سال بھی گزارے ہیں لیکن اب ایک کیفیت سامنے آئی ہے جسے ’خلائی انیمیا‘ کا نام دیا گیا ہے۔ پہلے خیال تھا کہ یہ ایک عارضی کیفیت ہے جو بعد میں ٹھیک ہوجاتی ہے۔ تاہم اب مفصل تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے اثرات طویل عرصے تک جاری رہتے ہیں۔
اس کے لیے بین الاقوامی خلائی تحقیقی اسٹیشن (آئی ایس ایس) میں وقت گزارنے والے 14 خلانوردوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر خلانوردوں نے سانس لینے میں دقت کا اظہار بھی کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خلانوردوں کے خون کا تجزیہ خلائی اسٹیشن کے قیام کے دوران کیا گیا۔
جامعہ اوٹاوا کے سائنسداں ڈاکٹر گائے ٹروڈل اور ان کے ساتھیوں نے اندازہ لگایا کہ جب کچھ ماہ بعد خلانوردوں نے زمین پر قدم رکھا توفی سیکنڈ خون کے 20 لاکھ سرخ خلیات تباہ ہورہے تھے جبکہ خلا میں یہ شرح 30 لاکھ خلیات فی سیکنڈ تھی۔
خلا کے خردثقلی ماحول میں انسانی جسم 20 فیصد مائع کھودیتا ہے اور سراورسینے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ پھرزمین پر آنے کے چارماہ بعد بھی خلیات کے تباہ ہونے کی شرح اوررفتار برقرار رہی۔
تمام خلانوردوں کا خون جانچنے کے بعد اگرچہ انہیں انیمیا کا شکار نہیں کہا گیا لیکن ان کی غذا تبدیل کرنے اور مزید تحقیق پر زوردیا گیا ہے۔
https://www.express.pk/story/2272551/9812/
شوگر کے 15 فیصد مریضوں کو پاؤں میں زخم ہونے کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کیفیت کو طبی اصطلاح میں (diabtic foot ulcer) کہا جاتا ہے۔ ان زخموں کا کامل علاج طویل عرصے پر محیط ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی دوبارہ انفیکشن کا خطرہ باقی رہتا ہے۔ یہ زخم 70 فیصد کیسز میں عضو کو کاٹنے کی وجہ بھی بنتے ہیں۔
تاہم بھارتی ماہرین کی ایک ٹیم نے تحقیق کے ذریعے شوگر کی وجہ سے پاؤں کے زخموں کو دنوں میں مندمل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارت کی بنارس ہندو یونیورسٹی (بی ایچ یو) کے مائیکروبائیولوجی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر گوپال ناتھ اور ان کی ٹیم نے روایتی طریقہ علاج جس میں اینٹی بائیٹوکس شامل ہوتی ہیں کو چھوڑ کر متبادل طریقہ علاج اپنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس پر مشتمل علاج میں سالوں لگ سکتے ہیں جبکہ اس میں انفیکشن کے دوبارہ ہونے کے چانسز بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔
سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ bacteriophage therapy جس میں وائرسز کی مدد سے انفیکشن کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اینٹی بائیوٹک مزاحم بیکٹیریاؤں کا جدید حل ہے۔
ماہرین نے بیکٹیریوفیج تھیراپی کا تجربہ ایسے ہی مریضوں پر کیا اور نتائج نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ امریکا کے نیشنل سینٹر فار بائیوٹیکنالوجی انفارمیشن میں شائع کروائے۔
تحقیق میں ایسے 20 مریضوں کو چُنا گیا جو 6 ہفتوں سے شوگر کی وجہ سے پاؤں کے غیر مندمل زخم میں مبتلا تھے۔ تھیراپی کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ زخم چند ہی ہفتوں میں مندمل ہوگیا اور زخم شدہ کھال پہلے جیسی نارمل حالت میں آگئی۔
ایک اور تحقیق میں 48 مریضوں کو چُنا گیا جن کا زخم 6 ہفتوں سے ٹھیک نہیں ہوا تھا اور وہ زخم کے روایتی علاج و احتیاط جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان میں بھی بیکٹیریوفیج تھیراپی کے فوری اثرات کا مشاہدہ کیا گیا اور زخم مکمل طور پر ٹھیک ہوگیا۔
تحقیق بتاتی ہے کہ یہ طریقہ علاج، شوگر کا مرض ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں موثر ہے۔ تاہم شوگر کے مریضوں میں زخم مندمل ہونے میں تھوڑا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2272871/9812/
اٹلی کے ’لازارینی ڈیزائن اسٹوڈیو‘ نے ایک ایسی پرآسائش اور دیوقامت کشتی کا ڈیزائن پیش کیا ہے جو ہوا میں اُڑے گی اور پانی پر اُتر سکے گی۔ اسے ’ایئر یاٹ‘ کا نام دیا گیا ہے۔
بنیادی طور پر یہ دو ایئرشپس کا مجموعہ ہوگی جنہیں درمیان میں ایک مرکزی ڈھانچے (hull) کے ساتھ جوڑا جائے گا۔
ان میں سے ہر ایئرشپ میں 2 لاکھ مکعب میٹر ہیلیم گیس بھری ہوگی جو اسے فضا میں بلند رکھنے میں مددگار ہوگی۔

دورانِ پرواز رفتار یا سمت تبدیل کرنے کےلیے اس میں چار بڑے پنکھے (روٹر) بھی نصب ہوں گے جو ایئر شپس میں لگی ہوئی بیٹریوں سے بجلی حاصل کریں گے جبکہ بیٹریوں کو ان ایئر شپس کی چھتوں پر نصب وسیع شمسی پینلوں سے چارج کیا جائے گا۔

لازارینی ڈیزائن اسٹوڈیو کے مطابق، اس ’ایئر یاٹ‘ میں 22 مسافر بہت آرام سے رہ سکیں گے۔
ایئر یاٹ کو ہوا میں بلند کرنے کےلیے اس میں بھری ہیلیم گیس کو پھیلنے دیا جائے گا جو ہوا سے ہلکی ہوکر اسے آہستہ آہستہ اوپر اٹھا لے گی۔
اس کے برعکس، جب یہ ہیلیم دباکر اس کی کثافت بڑھائی جائے گی تو ایئر یاٹ بھی بتدریج نیچے اترتی جائے گی۔

ایئر یاٹ کو ہلکے پھلکے لیکن مضبوط فائبر سے تیار کیا جائے گا جبکہ اس کے دائیں بائیں والی ایئر شپس کو آٹھ ’سرنگوں‘ کے ذریعے مرکزی حصے سے جوڑا جائے گا۔
جسامت کی بات کریں تو ایئر یاٹ میں ایئر شپس والے حصے کی لمبائی 492 میٹر ہوگی جبکہ درمیانی حصہ 262 فٹ لمبا ہوگا، جس کی چوڑائی 33 فٹ رکھی جائے گی۔
ایئر یاٹ دائیں اور بائیں حصوں میں مسافروں کےلیے پر آسائش کمرے ہوں گے جہاں وہ آرام کرنے کے علاوہ بڑی بڑی کھڑکیوں سے آسمان اور سمندر کا نظارہ بھی کرسکیں گے۔
درمیان والا حصہ شفاف ہوگا جس میں ماسٹر کیبن، عارضی آرام گاہ اور ڈائننگ ایریا ہوں گے جہاں سمندر سے آسمان تک 360 ڈگری کا مکمل منظر دیکھا جاسکے گا۔

ایئر یاٹ زیادہ سے زیادہ 111 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرسکے گی جبکہ اس کی بیٹریوں کو دو دن (48 گھنٹے) بعد چارج کرنے کی ضرورت پڑے گی۔

البتہ، سمندر کی سطح پر اترنے کے بعد اس کی رفتار صرف 9 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جائے گی۔
ایئر یاٹ کے مسافر اگر چاہیں گے تو کشتی کے ذریعے ساحل تک جاسکیں گے اور اگر انہیں جلدی ہو تو اس کےلیے ایئر یاٹ کے مرکزی حصے کی چھت پر ایک عدد ہیلی پیڈ بھی موجود ہوگا جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اپنی منزلِ مقصود کی طرف تیزی سے پرواز کرسکیں گے۔

اپنی تمام خوبیوں اور ماحول دوست خصوصیات کے باوجود، ایئر یاٹ کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا خاصا مشکل ہوسکتا ہے کیونکہ آج بھی بیسویں صدی کے آغاز میں ایئر شپ ’ہنڈنبرگ‘ کے خوفناک حادثے کی یادیں کسی آسیب کی طرح مسلط ہیں۔
1937 کے اس سانحے میں جرمنی کی مشہور ایئر شپ ’ہنڈنبرگ‘ میں اچانک آگ لگ گئی تھی اور اس میں سوار 36 مسافر دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاک ہوگئے تھے۔
ایئر یاٹ کی راہ میں دوسرا بڑا چیلنج اس کا تفریحی مقصد اور پرواز کی لاگت ہے جو ممکنہ طور پر عام فضائی سفر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔
اس وقت مختلف ادارے ایسی طاقتور اور ماحول دوست ’کارگو ایئرشپس‘ پر کام کررہے ہیں جو تجارتی سامان کو موجودہ بحری جہازوں کے مقابلے میں صرف 25 فیصد لاگت پر ایک سے دوسری جگہ پہنچاسکیں گی۔
کیا ایسی صورتِ حال میں کوئی شخص محض تفریح کی خاطر ایئر یاٹ میں سفر پر ہزاروں ڈالر خرچ کرے گا؟ فی الحال اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔
https://www.express.pk/story/2272709/508/
ہارٹ فیل ہونے کی ایک قسم سے مریض کے معمولات شدید متاثر ہوتے ہیں اور اسے بار بار ہسپتال جانا پڑتا ہے تاہم اب دل میں نصب کرنے والا ایک پیوند اس مشکل کو آسان کرسکتا ہے۔
اسرائیلی کمپنی ’ریسٹور میڈیکل‘ نے اسے تیار کیا ہے جسے ’کونٹرا بینڈ‘ کا نام دیا گیا ہے۔ دل کی بیماری ’کنجیسٹو ہارٹ فیلیئر‘ یا سی ایچ ایف میں دل اتنا کمزور ہوجاتا ہے کہ خون دھکیلنے یا پمپ کرنے کی قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس میں متبلا افراد مشکل سے 5 تا 10 برس زندہ رہتے ہیں۔ وینٹریکل یا والو سے خون باہر نہیں نکل پاتا اور دل کا خون اور مائع پھیپھڑوں تک پہنچتا رہتا ہے۔
سی ایچ ایف میں پورے بدن کو مناسب لہو نہیں پہنچ پاتا اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ مریض چند قدم چلنے کے بعد تھک جاتا ہے اور ہانپنے لگتا ہے۔ جاننا ضروری ہے کہ سی ایچ ایف میں دل مردہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے خون پھینکنے کی قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ عموماً اس میں الٹا والو یا وینٹریکل بے کار ہوجاتا ہے۔
اب ایک تار نما آلہ دل میں لگا کر اس کیفیت کو بہت حد تک دور کیا جاسکتا ہے۔ اسے پلمونری شریان میں لگایا جاتا ہے۔ یہ صحت مند سیدھے والو کے پریشر کو نوٹ کرتے ہوئے اس کا پریشر بڑھا دیتا ہے جس سے الٹے والو کی ناکارگی کا ازالہ ہوتا رہتا ہے۔
اسے عین اینجیو پلاسٹی کی طرح ایک تار سے دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک گھنٹے کے عمل کے بعد مریض اگلے دن گھر جاسکتا ہے۔
اس طرح مریض کی کیفیت بہتر ہوجاتی ہے۔ دوا کے ساتھ ساتھ فائدہ ہوتا ہے اور مریض بار بار ہسپتال جانے سے بچ رہتا ہے۔ پہلے اسے جانوروں پر آزمایا گیا دوسرے مرحلے میں تین انسانوں پر اس کی آزمائش شروع کی گئی۔
یہ 2026ء تک دنیا بھر کے لیے عام دستیاب ہوگا تاہم ایف ڈی اے کی منظوری کی شرط اپنی جگہ موجود ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ اس دوران وہ مزید انسانوں پرآزمائش کرے گی۔
کونٹرا بینڈ کی تنصیب کے بعد کوئی پیچیدگی پیدا ہونے کے بعد اسے دوبارہ باہر نکالنے کی بجائے دل کے اندر ہی غیر سرگرم کیا جاسکتا ہے اور مریض کو کچھ نہیں ہوتا۔
https://www.express.pk/story/2272210/9812/
ماہرینِ فلکیات کی ایک عالمی ٹیم کا کہنا ہے کہ ہمارے نظامِ شمسی کے گرد عظیم الشان اور پراسرار ’کائناتی بلبلہ‘ اُن واقعات کے تسلسل کا نتیجہ ہے جو آج سے ایک کروڑ 40 لاکھ سال پہلے شروع ہوئے تھے۔
واضح رہے کہ ماہرین تقریباً چالیس سال سے جانتے ہیں کہ ہمارے نظامِ شمسی کے گرد تقریباً 1,000 نوری سال وسیع علاقے کے اندر بہت کم ستارے ہیں جبکہ اس کے باہر نئے ستارے خاصی بڑی تعداد میں بن رہے ہیں۔ فلکیاتی اصطلاح میں یہ علاقہ ’لوکل ببل‘ جبکہ عوامی زبان میں ’کائناتی بلبلہ‘ کہلاتا ہے۔
نئی تحقیق میں امریکا، جرمنی، آسٹریا اور کینیڈا کے ماہرین نے حالیہ برسوں میں کیے گئے تفصیلی اور حساس فلکیاتی مشاہدات اور پیچیدہ کمپیوٹر سمیولیشنز کی مدد سے دریافت کیا کہ یہ ’کائناتی بلبلہ‘ 14 ملین (ایک کروڑ 40 لاکھ) سال پہلے ایک سپرنووا دھماکے سے بننا شروع ہوا تھا۔
سورج سے کئی گنا زیادہ کمیت والا کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک شدید دھماکے سے پھٹتا ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ توانائی، صدماتی لہریں اور اس ستارے کا مادہ چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ یہی وہ دھماکہ ہے جسے ’سپرنووا‘ کہا جاتا ہے۔
14 ملین سال پہلے سپرنووا کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والے اس کائناتی بلبلے کے بیرونی کناروں پر نئے ستارے بھی بڑی تعداد میں بننے لگے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔
البتہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بلبلہ مسلسل پھیلتا چلا گیا اور آج تقریباً 1,000 نوری سال جتنا وسیع ہوچکا ہے۔
تازہ تحقیق میں ماہرین نے نہ صرف اس کائناتی بلبلے کی پوری تاریخ معلوم کی ہے بلکہ اس کی ساخت کا تعین بھی کیا ہے۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کائنات میں ایسے وسیع و عریض بلبلوں کی بڑی تعداد موجود ہوسکتی ہے لیکن اس کےلیے ہمیں مزید تحقیق کرنا ہوگی۔
نوٹ: اس تحقیق کی تفصیلات ریسرچ جرنل ’’نیچر‘‘ کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔
https://www.express.pk/story/2270804/509/
امریکی سائنسدانوں نے ایک ایسا ننھا منا آلہ ایجاد کرلیا ہے جسے ماسک میں لگا کر سانس اور دل دھڑکنے کی رفتار معلوم کی جاسکتی ہے۔
اس آلے کو انہوں نے اسمارٹ واچ کے ذریعے صحت پر نظر رکھنے والے ’فٹ بِٹ‘ (FitBit) کی طرز پر ’فیس بِٹ‘ (FaceBit) کا نام دیا ہے۔
فیس بِٹ کی جسامت ایک چھوٹے سکّے جتنی ہے اور اسے کسی بھی این 95 ماسک میں ایک مقناطیس سے چپکایا جاسکتا ہے۔

اگرچہ اس کی بیٹری کئی دن تک کام کرتی ہے لیکن یہ اپنے پہننے والے کی سانسوں، جسمانی گرمی اور سورج کی روشنی تک سے خود کو چارج کرتی رہتی ہے؛ اور اس طرح اسے ایک بار چارج ہوجانے کے 11 دن بعد دوبارہ چارجنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔
’فیس بِٹ‘ میں سانسیں اور دھڑکنیں نوٹ کرنے والے حساسیے (سینسرز) نصب ہیں جو اپنی جمع کردہ معلومات فوری طور پر ایک مرکزی نظام کو بھیجتے رہتے ہیں۔
یہ نظام مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہوئے سانسوں اور دھڑکنوں کی رفتار کو صحت کی متعلقہ کیفیات میں تبدیل کرتا ہے اور اگر ان میں کوئی خلافِ معمول تبدیلی نوٹ کرتا ہے تو اس کی اطلاع بھی وہ فوراً ہی ایک عدد موبائل ایپ کے ذریعے اس فرد کو یا متعلقہ حکام کو دیتا ہے۔
سانسوں اور دھڑکنوں کے علاوہ ’فیس بِٹ‘ اس پر بھی نظر رکھتا ہے کہ ماسک ڈھیلا یا لیک تو نہیں ہوگیا۔
یہ آلہ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی، الینوئے میں الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر ہوزیاہ ہیسٹر اور ان کے ساتھیوں نے ایجاد کیا ہے جسے فی الحال اسپتالوں میں کام کرنے والے طبّی عملے پر کامیابی سے آزمایا جاچکا ہے۔
اس ایجاد یعنی ’فیس بِٹ‘ کی تفصیلات ’پروسیڈنگز آف دی اے سی ایم آن انٹریکٹیو، موبائل، ویئریبل اینڈ یوبیکیٹس ٹیکنالوجیز‘ کی تازہ ترین اشاعت میں شائع ہوئی ہیں۔
https://www.express.pk/story/2270752/9812/
ہم جانتے ہیں کہ جوڑوں کے درد میں ہڈیوں اور جوڑوں کے درمیان موجود نرم اور کرکری ہڈی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ اور گھساؤ کی شکار ہوجاتی ہیں۔ اب بجلی خارج کرنے والے ایک نظام سے اس نرم ہڈی کی افزائش بڑھا کر اس کیفیت کی شدت کم کی جاسکتی ہے۔
سب سے پہلے اس کا پیوند یا امپلانٹ ایسے چوہوں پر آزمایا گیا جو حرکت کرتے تھے اور ہلکی بجلی بنتی تھی اور وہ ٹوٹی ہوئی نرم ہڈیوں تک پہنچتی تھی۔ اس طرح ان کی ہڈیوں کی درمیان ربڑ جیسی چکنی تہہ کی افزائش ازخود شروع ہوگئی۔ تاہم بعض خرگوشوں میں فرضی آلہ(بلے سیبو) لگایا گیا تھا جس کا کوئی فائدہ سامنے نہیں آیا۔
یہ تحقیق جامعہ کنیکٹکٹ امریکا کے سائنسدانوں نے کی ہے۔ انہوں نے جسم کے اندر بیٹری لگانے کی بجائے ایسا مادہ لگایا ہے جو جسمانی حرکت اور دباؤ سے بجلی بناتا ہے اور جوڑوں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ یوں نرم ہڈی کے خلیات بڑھے اور ان میں حرکت پیدا ہوئی اور دھیرے دھیرے ان کی تکلیف کم ہوتی گئی۔
سائنسدانوں نے بجلی خارج کرنے والا نرم پیوند خرگوشوں کی ان کرکری ہڈیوں کے سوراخوں میں پھنسایا تھا جس گھس کر ختم ہورہی تھیں۔ خردبین سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ دھیرے دھیرے اصل ہڈی کے خلیات اس جگہ کو بھرنے لگے اور یہ سب ہلکی بجلی کی بدولت ممکن ہوا تھا۔
https://www.express.pk/story/2270917/9812/
اس کار کو دیکھ کر آپ کچھ بھی کہیں لیکن یہ بیٹ مین کی گاڑی لگتی ہے اور اپنے جدید ترین ڈیزائن کی بنیاد پر رن وے کے بغیر سیدھا اوپر اٹھنے والے کار ہے جس کی کامیاب آزمائش دبئی میں کی گئ ہے۔
برطانوی کمپنی بیل ویدر نے اسے بنایا ہے اور اس کی نصف جسامت (ہاف اسکیل) ماڈل نے ٹیسٹ فلائٹ میں متوقع نتائج دکھائے ہیں جس کی ویڈیو دیکھ کرآپ خود حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ اسے وولر ای وی ٹی او ایل کا نام دیا گیا ہے۔ ماہرین اسے ہائپرکار قرار دے رہے ہیں۔

نصف جسامت پر اڑنے کے باوجود اس نے سائنسدانوں اور انجینیئروں کا دل خوش کردیا ہے ۔ دیکھنے والے اس کے ڈیزائن ار خوبصورتی کے متعرف ہوگئے ہیں۔ نظری طور پر یہ 135 (215 کلومیٹر) میل فی گھنٹہ کی رفتار سے لگ بھگ 3000 فٹ کی بلندی پر جاسکتی ہے۔
ماحول دوست، برق رفتار اور بے آواز وولر کارمکمل طور پر برقی توانائی سے چلتی اور پرواز کرتی ہے۔ کمپنی کے مطابق اس کا اولین نمونہ نومبر 2021 میں تیارہوچکا تھا۔ بس کمپنی بہترموقع کی تلاش میں تھی اور اب اسے دبئی میں اڑا کر اس کی پہلی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو بی ویدر کے آفیشل یوٹیوب اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ہے۔

آٹوموبائل تجزیہ کار ماہرین نے اس کی ڈیزائننگ، افادیت اور کارکردگی کو متاثرکن اور امید افزا قرار دیا ہے۔ ویڈیو میں اسے اوپراٹھتے دیکھا جاسکتا ہے لیکن یہ ہوا میں سیدھی رہنے کی بجائے ادھر ادھر ڈولتی دکھائی دیتی ہے ۔ اس خامی کو شاید اگلے مراحل میں دور کیا جائے گا۔
تکنیکی طور پر وولر ملٹی کاپٹر سواری ہے جس کے پنکھے اس کے ڈیزائن کے اندر چھپائے گئے ہیں۔ لیکن اس میں اضافی پروپلشن کا معلوم نہیں ہوسکا ہے۔ تاہم ڈیزائن سے دو دونشستی اڑن کار ہے۔ لیکن کمپنی کے مطاق اگلے ڈیزائن میں چار سے پانچ افراد بیٹھ سکیں گے۔ ایک مرتبہ چارج ہونے کے بعد یہ ڈیڑھ گھنٹے تک پرواز کرسکے گی۔
کمپنی نے اس کی کوئی قیمت نہیں بتائی ہے لیکن اتنا ضرور بتایا ہے کہ تجارتی تیاری 2028 میں شروع ہوجائے گی۔
https://www.express.pk/story/2270532/508/
https://e.dunya.com.pk/detail.php?date=2022-01-13&edition=KCH&id=5916045_82802380
اب یہ ممکن ہے کہ آنکھوں میں لگائے جانے والے لینس مجھے اور آپ کو ذیابیطس سمیت کئی امراض کی خبر دے سکتے ہیں۔ لینس جدید ترین مائیکروچپ اور حساس سینسر بھی لگے ہیں۔
کیلیفورنیا میں واقع اِن ودھ نامی کمپنی نے برسوں کی محنت سے اسے تیار کیا ہے جس میں مرکزی لینس لچکدار ہائیڈروجل سے بنایا گیا ہے۔ اس کے کنارے پر مائیکروالیکٹرانکس کا کمال ہے جس کی بدولت باریک سرکٹ، سینسر اور مائیکروچپ لگائی گئی ہیں۔ اتنے نظام کے باوجود کوئی بھی شے آنکھوں میں محسوس نہیں ہوتی۔
لینس کے اندر بچھا ہوا پورا نظام آنکھوں کے اندر کی جسامت، شکل اور بیرونی سطح کا خیال رکھتا ہے۔ اگر آنکھوں میں خون کی باریک ترین رگوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا ریٹینا میں کچھ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو اس کی فوری خبر مل جاتی ہے۔ اس کا ڈیٹا حقیقی وقت میں ایپ کی بدولت اسمارٹ فون اور کمپیوٹر تک پہنچتا رہتا ہے۔
لینس میں یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ سبزموتیا یا گلوکوما اور دیگر بیماریوں کا پتا لگا سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی طرح خون میں شکر کی مقدار بڑھتی ہے تو لینس پہننے والے کو اس کا علم ہوجائے گا۔ اس طرح ہم لینس کو آنکھوں میں سمائے ہوئے ڈاکٹر سے تعبیر کرسکتے ہیں۔
ان ودھ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دنیا کا پہلا نرم برقی سرکٹ والا کانٹیکٹ لینس بنایا ہے۔ تاہم کمپنی نے اس کی قیمت کا اعلان نہیں کیا ہے۔
https://www.express.pk/story/2269991/9812/
خوب سے خوب تر کی تلاش میں ایک کمپنی نے اب ایسا وائرلیس ہیڈفون بنایا ہے جو ایک جانب تو بہترین معیار کی آواز سناتا ہے اور دوسری جانب اطراف کی ہوا کو دھوئیں، آلودگی، جراثیم، وائرس اور دیگر اقسام کے بیکٹیریا سے محفوظ رکھتا ہے۔
اسے اِبل نامی کمپنی نے تیارکیا ہے اور اس کے مطابق یہ ہیڈ فون کے ساتھ ہوا کو صاف کرنے والا (ایئر پیوریفائر) نظام ہے۔ اس میں خردبینی نظام سمویا گیا ہے جو ہوا میں ایسے مرکبات شامل کرتا رہتا ہے جس سے بیکٹیریا، جراثیم، سگریٹ کے دھویں اور دیگر اقسام کے وائرس کی 99 فیصد تعداد ختم ہوجاتی ہے۔
اَبل کمپنی نے اسے پہنے جانے والا (ویئرایبل) ایئرپیوریفائرکہا ہے۔ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ گاڑیوں سے خارج ہونے والے انتہائی مضر ذرات پی ایم 2.5 کو تلف کیا جاسکتا ہے۔ تاہم کمپنی نے ایک اور دعویٰ یہ ہے کیا ہے کہ ان کی ایجاد کووڈ 19 وائرس بھی ختم کرسکتا ہے۔

اس کمپنی نے ایل ون، سی ون اور ایم ون نامی تین ماڈل بنائے ہیں جن میں سے ایک ہیڈفون کے ساتھ بنایا گیا ہے جبکہ دو لاکٹ اور ہار جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ایئرویڈا کے تمام ماڈلوں کو بہت ہلکا پھلکا اور خوبصورت بنایا گیا ہے جسے دیکھنے کے بعد خریدنے کو دل کرتا ہے۔ اس کا ڈیزائن اتنا بہتر اور ہلکا پھلکا ہے کہ اسے گلے میں لٹکایا جاسکتا ہے۔
تائیوان اور جرمنی کے ماہرین نے اسے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نے کئی تجربہ گاہوں میں اپنی مضوعات کی جانچ پڑتال کرائی ہے اور اس کے بہترین نتائج برآمد ہوئے ہیں۔
اس کا دل و دماغ ایک برقی نظام ہے جو باریک جھریوں سے فی مکعب سینٹی میٹر 20 لاکھ منفی چارج والے آئن خارج کرتا ہے۔ منفی آئن جراثیم، وائرس اور آلودگی کے ذرات کو دھکیلتا ہے۔
جب آئن جراثیم، آلودہ ذرات اور وائرس وغیرہ سے چپکتے ہیں تو وہ بھاری ہوکر نیچے گرنے لگتے ہیں اور آپ کے منہ تک نہیں پہنچ پاتے۔
پورا ہیڈ فون مشکل سے 70 گرام وزنی ہے اور پہننے پر بھاری محسوس نہیں ہوتا جب کہ ایک بار چارج ہونے کے بعد 32 گھنٹےتک کام کرتا رہتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2269755/9812/
آبِ حیات؟ جاپانی سائنسدانوں نے بڑھاپا اور موت کا سبب بننے والے خلیات کے خلاف ویکسین تیار کرلی
Dec 13, 2021 | 22:32:PM

سورس: Wita
ٹوکیو (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک جاپانی ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے اس نے ایک ایسی ویکسین تیار کرلی ہے جو جسم کے اندر موجود ان زومبی سیلز کو ختم کردے گی جو نہ صرف قریبی صحت مند سیلز کو تباہ کرتے ہیں بلکہ جسم میں بڑھاپا اور شریانوں میں کھنچاؤ پیدا کرتے اور موت کا سبب بنتے ہیں۔
دی جاپان ٹائمز کے مطابق تحقیق میں شامل جوتیندو یونیورسٹی کے پروفیسر تورو منا مینو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس ویکسین نے چوہوں میں کامیابی کے ساتھ زومبی اور اعصابی کھنچاؤ پیدا کرنے والے سیلز کو ختم کیا ہے۔ "ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ویکسین انسانوں میں ذیابیطس اور بڑھاپے سے متعلق دیگر بیماریوں کے خلاف استعمال کی جاسکتی ہے۔"
اس تحقیق کے نتائج آن لائن ریسرچ جرنل نیچر ایجنگ میں شائع کیے گئے ہیں۔ زومبی سیلز جسم کے وہ خلیات ہوتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتے اور نہ ہی مرتے ہیں بلکہ ایسے کیمیکلز چھوڑتے ہیں جو صحت مند خلیات کی موت کا باعث بنتے ہیں۔
محققین نے زومبی سیلز میں ایک پروٹین کو ڈھونڈا اور اس کے خلاف ویکسین تیار کرکے اعصابی کھنچاؤ میں مبتلا چوہوں کو لگائی تو نہ صرف زومبی سیلز کا خاتمہ ہوگیا بلکہ جسم کے متاثرہ حصے بھی ٹھیک ہوگئے۔ جب یہی ویکسین بوڑھے چوہوں کو لگائی گئی تو ان میں دیگر چوہوں کی نسبت بڑھاپے کا عمل سست ہوگیا۔
ماہرین نے بتایا کہ زومبی سیلز کے خاتمے کیلئے پہلے سے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ اینٹی کینسر ہوتی ہیں جن کے سائڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن نئی ویکسین کے سائڈ ایفیکٹس بہت کم تھے اور اس کا اثر دیر تک برقرار رہا۔
https://dailypakistan.com.pk/13-Dec-2021/1377491?fbclid=IwAR2nl9crzXFKmn32Rw25C4qVjl_AdbjtSkc9UPok5famm2rll74y-5SQcMs
ناسا سمیت دنیا کے کئی ماہرین نے اب سکون کا سانس لیا ہے کیونکہ اب جیمز ویب خلائی دوربین کی کائنات بینی کے دو اہم مراحل مکمل ہوچکے ہیں ۔ پہلے پردوں کی صورت میں لپٹی شمسی حفاظتی چادر کھولی گئی اور اس کے بعد اس کے درجن سے زائد حصوں پر مشتمل مرکزی آئینے عین منصوبے کے تحت کھولے جاچکےہیں۔ اس کے بعد دنیا کو اس کی پہلی تصویر کا انتظار ہے۔ واضح رہے کہ آئینے کھلنے کے بعد اس کا رقبہ 21 فٹ ہے۔
ماہرین کے مطابق 8 جنوری کو ای ایس ٹی کے مطابق سوا بجے دوپہر کو جیمزویب اسپیس ٹیلی اسکوپ نے اپنے آئینے کھول دیئے تھے۔ ناسا نے اسے فائنل ان فولڈنگ مرحلے کا اہم نام دیا تھا۔
ناسا کی یہ دوربین اس قدر بڑی تھی کہ اسے کسی بھی راکٹ پر نصب کرنا ممکن نہیں تھا، اسی باعث اس کے مختلف حصوں کو بند (فولڈ) کیا گیا تھا تاکہ وہ سکڑ کر ایک راکٹ کے پے لوڈ میں سماسکیں۔
یہ مرحلہ اتنا مشکل اور حساس تھا کہ معمولی سی غلطی اربوں ڈالر کی رقم اور عشروں کی محنت اکارت ہوسکتی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ پوری دوربین کو کھولنے کے لیے 344 مراحل تھے جن کا مکمل درستگی سے انجام پانا ضروری تھا۔
جیمزویب دوربین میں دوطرح کے آئینے لگے ہیں۔ اول مرکزی آئینہ ہے جو بصری آئینہ اور 18 ہشت ساختہ (اوکٹینگل) شکل رکھتے ہیں۔ مرکزی آئینے کے اوپر دوسرا ثانوی آئینہ دھاتی سلاخوں سے جڑا ہے۔ تیسرے اور اہم گوشے میں جدید ترین سائنسی آلات اور کیمرے موجود ہیں۔
اب یہ زمین سے لگ بھگ دس سے گیارہ لاکھ کلومیٹر دور رہتے ہوئے ایل ٹو نامی مدار میں زیرِ گردش ہے۔ اس کے وسیع آئینے مرئی، انفراریڈ اور دیگر اقسام کی روشنیوں کو دیکھ کر ہمیں کائنات کی قدیم ترین صورت دکھاسکیں گے۔ توقع ہے کہ اربوں سال پہلے تشکیل پانے والی اولین کہکشاؤں کا نظارہ بھی ہماری بصارت تک پہنچے گا۔
https://www.express.pk/story/2269405/508/
ہم جانتے ہیں کہ ہاتھوں کے اشارے سے کمپیوٹرکے بہت سارے فیچرقابو کئے جاسکتے ہیں جس کے کئی سسٹم بن بھی چکے ہیں۔ لیکن ٹائپ الائک سسٹم کی بدولت مہنگے ہارڈویئر کی بجائے ویب کیم میں معمولی تبدیلی کرکے ہاتھوں کے 36 اشاروں کو 97 فیصد درستگی سے سمجھ کر کمپیوٹر مختلف کام انجام دے سکتا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے کسی نئے ہارڈویئراور برقی نظام کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ یوں کسی بھی ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ کو ہاتھوں کے اشارے سے چلایا جاسکتا ہے۔
ٹائپ الائک سسٹم کینیڈا کی جامعہ واٹرلو نے تیار کیا ہے۔ اس میں صرف دو اجزا ہیں ۔ ایک چھوٹا آئینہ ہے جو خاص زاویئے سے جھکاکر ویب کیم پر لگایا جاتا ہے اور دوسری شے ایک جدید الگورتھم یا سافٹ ویئر ہے۔

اب اگرآپ کمپیوٹر کی آواز بڑھانا چاہتے ہیں ایک ہاتھ کمپیوٹر پر رہنے دیں اور دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اوپر اٹھائیں جو تھمبس اپ کہلاتا ہے۔ اس طرح سافٹ ویئر اشارہ سمجھ کرآواز بلند کردیتا ہے۔
جامعہ میں کمپیوٹرسائنس کے طالبعلم نیلن شیبار نے یہ نظام بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ویب کیم چہرے کو دیکھتا رہتا ہے اور ہاتھ اوجھل رہتے ہیں۔ اس لیے نیچے کی جانب ایک ترچھا آئینہ لگایا گیا ہے جوہاتھوں کو دیکھتا رہتا ہے۔
ہرفرد کے ہاتھوں کے اشارے مختلف ہوسکتے ہیں اور اسی لیے سائنسدانوں نے 30 مختلف رضاکاروں کے ہاتھوں کے اشاروں کا ایک ڈیٹا بیس بنایا تاکہ اس کی بھی معیار بندی کی جاسکے۔ اس طرح 36 اشاروں سے کمپیوٹر کے 36 فیچر کنٹرول کئے جاسکتے ہیں۔ دوسری جانب اس کا الگورتھم مزید سیکھتا رہتا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدائی تجربات میں کمپیوٹر نے 97 فیصد درستگی سے ان تمام اشاروں کی درست ترجمانی کی جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔
https://www.express.pk/story/2269350/509/
ایک امریکی کمپنی ’جان ڈیئر‘ نے ایسا ٹریکٹر پیش کیا ہے جو خودکار طور پر ہل چلانے کے علاوہ کاشتکاری کے دوسرے متعلقہ کام بڑی مہارت سے انجام دے سکتا ہے۔
یہ ٹریکٹر امریکی شہر لاس ویگاس میں منعقدہ ’کنزیومر الیکٹرونکس شو 2022‘ میں رکھا گیا جو 5 سے 8 جنوری تک جاری رہی۔ یہ دنیا میں جدید ترین ایجادات کی سب سے بڑی سالانہ نمائش بھی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، اس ٹریکٹر کو ’ڈیئر 8 آر‘ (Deere 8R) کا نام دیا گیا ہے جو 40 ہزار پاؤنڈ (18 ٹن سے زیادہ) وزنی ہے۔
یہ اپنے اسٹیریو کیمروں کے چھ جوڑوں کی مدد سے کھیت پر نظر رکھتا ہے اور جی پی ایس سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے مطلوبہ راستوں پر ہل چلاتا ہے۔
اس کا خودکار نظام طاقتور مائیکروپروسیسرز، حساسیوں (سینسرز) اور مصنوعی ذہانت والے ایک پروگرام سے لیس ہے جو موبائل ایپ کے ذریعے کسان کے اسمارٹ فون سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔
کسان کو صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ وہ ٹریکٹر سے ہل یا کوئی دوسرا متعلقہ زرعی آلہ منسلک کرے اور ایپ کے ذریعے اس اراضی کی نشاندہی کردے کہ جہاں ٹریکٹر سے ہل چلانا یا کوئی اور کام لینا مقصود ہے۔
کسان کو مزید صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ایپ سے ٹریکٹر کو کام شروع کرنے کی ہدایت دے اور اس کے بعد چاہے تو اہلِ خانہ اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارے یا پھر کچھ اور کرے۔
یہ ٹریکٹر ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سارا کام خودکار طور پر سنبھالتا ہے جبکہ اس دوران وہ ہل چلانے کے علاوہ کھیت میں فصلوں اور مٹی کی صحت، مٹی میں نمی کی مقدار اور دوسری اہم زرعی معلومات بھی جمع کرتا رہتا ہے۔
اس پورے عمل میں ویسے تو کسان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کبھی کبھار ٹریکٹر کا سامنا کسی غیر متوقع صورتِ حال سے ہوجائے کہ جسے اس کا سافٹ ویئر سنبھالنے کے قابل نہ ہو، تو پھر اس کا نظام فوری طور پر ایپ کے ذریعے کسان کو اس کی خبر دیتا ہے تاکہ وہ اس مشکل یا رکاوٹ کا ازالہ کرنے کےلیے اس کی مدد کرے۔
جان ڈیئر کمپنی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر جیمی ہنڈمین کا کہنا ہے کہ خودکار ٹرک اور کار کے مقابلے میں خودکار ٹرک بنانا زیادہ مشکل کام تھا کیونکہ ٹریکٹر کو ان دوسری گاڑیوں سے کہیں زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مربوط ہونے کے علاوہ اپنی اپنی جگہ بہت پیچیدہ بھی ہوتے ہیں۔
اسی بناء پر وہ ’ڈیئر 8 آر‘ کو زرعی ٹیکنالوجی میں ایک نیا انقلاب قرار دے رہے ہیں۔ البتہ اب تک اس کی قیمت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
https://www.express.pk/story/2268749/508/
کسان نے اپنے مویشیوں کو سرد شام میں بھی دھوپ کا احساس دلانے کے لیے ورچوئل رئیلٹی چشمے لگادیے۔
ترکی سے تعلق رکھنے والے کسان ایزیٹ کو کاک کو سردیوں میں اپنی گائیں اندر لانا پڑتی ہیں لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ مویشیوں کو شام کے اوقات میں بھی دھوپ والی چراگاہوں اور ہری گھاس سے لطف اندوز ہونے احساس دلایا جائے۔
اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ اپنے مویشیوں کو ورچوئل رئیلٹی چشمے لگائے دیے تاکہ وہ یہ محسوس کریں کہ وہ درحقیقت دھوپ میں کچھ ہری بھرے کھیتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
انہوں نے دو گائے پر ہیڈ سیٹ آزمائے جب ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ خوشگوار مناظر مویشیوں کو زیادہ خوش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ زیادہ دودھ پیدا کرتی ہیں۔
کسان نے بتایا کہ اس تکنیک سے دودھ کی پیداوار 22 لیٹر سے 27 لیٹر روزانہ بڑھ رہی ہے۔
اس ضمن میں متعدد تکنیک استعمال ہورہی ہیں جو اپنے جانوروں کو خوش رکھنے اور زیادہ پیداواری کو یقینی بنانے کی کوشش کررہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے 180 جانوروں کے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے کلاسیکی موسیقی بجاتے ہیں اور وی آر سیٹ سے اتنا خوش ہیں کہ وہ مزید 10 ہیڈ سیٹ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
https://www.express.pk/story/2268517/10/
امریکی اسٹارٹ اپ کمپنی ’وائزیئر‘ (Wisear) نے ایسے ننھے منے ہیڈ فونز (ایئربڈز) ایجاد کرلیے ہیں جنہیں کنٹرول کرنے کےلیے صرف سوچنا ہی کافی رہتا ہے کیونکہ یہ دماغ کی لہریں پڑھ کر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔
ان ہیڈفونز کے ذریعے اپنی سوچ کی طاقت سے آپ منسلک ڈیجیٹل آڈیو پلیئر میں گانے تبدیل کرسکتے ہیں اور گانوں کی آواز بھی کم یا زیادہ کرسکتے ہیں۔
انہیں سوچ پڑھنے کے قابل بنانے کےلیے ان میں خاص طرح کے حیاتی حساسیے (بایو سینسرز) نصب ہیں جو چہرے کے پٹھوں اور دماغ میں ہونے والی سرگرمیوں کے سگنلز نوٹ کرتے ہیں اور، مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے، ان سگنلوں کو ہدایتی پیغامات (کنٹرول انسٹرکشنز) میں تبدیل کرتے ہیں۔
ہیڈ فونز سے متصل آڈیو پلیئر انہی کنٹرول انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہوئے آواز کم یا زیادہ کرتا ہے اور سننے والے کی خواہش کے مطابق آڈیو ٹریک بھی تبدیل کردیتا ہے۔
وائزیئر پچھلے سات سال سے اس ٹیکنالوجی پر کام کررہی تھی جسے اس سال پہلی بار ’’کنزیومر الیکٹرونکس شو‘‘ (سی ای ایس 2022) میں پیش کیا گیا ہے جو دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی عالمی نمائش ہے جو ہر سال امریکی شہر لاس ویگاس میں منعقد ہوتی ہے۔
وائزیئر کے مطابق، یہ ٹیکنالوجی اب اتنی پختہ ہوچکی ہے کہ اسے ورچوئل رئیلیٹی ہیلمٹس یعنی ’وی آر ہیڈ سیٹس‘ کا حصہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2268360/508/
انسانوں اور بیکٹیریا کی لڑائی طویل عرصے سے جاری ہے کیونکہ بیکٹیریا تیزی سے اپنی صورت بدل کرمزید سخت جان اور خطرناک ہوتے جارہے ہیں۔ اب مٹی میں ایک نئے مرکب کا انکشاف ہوا ہے جو عموماً اسپتالوں میں پائے جانے والے بیکٹیریا کو ختم کرسکتا ہے۔
اسپتالوں میں انفیکشن کی وجہ بننے والا سب سے اہم جرثومہ ایسینیٹو بیکٹر بومینیائی ہے جو ہر دوا کو بے اثر بنارہا ہے۔ اسپتالوں میں گھومنے والا یہ بیکٹیریا نہ صرف پینسلین اور ٹیٹراسائیکلین جیسی اہم اینٹی بایوٹک ادویہ کو ناکام بنارہا ہےبلکہ جراثیم کے خلاف ہمارا آخری ہتھیار کولسٹائن بھی اس سے ہار مان رہا ہے۔ اگر یہ دوا ناکام ہوجائے تو مریض مکمل طور پر انفیکشن کی زنجیروں میں قید ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود عالمی ادارے خبردار کررہے ہیں کہ ہم خطرناک بیکٹیریا کے خلاف اپنی جنگ ہار رہے ہیں اور اگر یہ رحجان جاری رہا تو چند عشروں بعد ہی ناقابلِ علاج بیکٹیریا کے اثرات سالانہ کروڑوں جانوں کا خراج لینے لگیں گے۔
وجہ یہ ہے کہ کولسٹائن کا استعمال بڑھا تو بالخصوص ایسینیٹو بیکٹر بومینیائی تیزی سے بدلا اور اب اس دوا کی افادیت کم کررہا ہے۔ ماہرین نے خود مٹی میں اسی بیکٹیریا کا ایک رشتے دار ڈھونڈا۔ اس کے لیے 10 ہزار بیکٹیریا کے جینوم کو پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ 35 جین ایسے ہیں جو کولسٹائن جیسی ساخت اور مزاج رکھتے ہیں۔ اس طرح کئی مراحل سے گزر کر تجربہ گاہ میں ایک مرکباتی سالمہ (کمپاؤنڈ مالیکیول) بنایا گیا جسے ’میکولیسن‘ کا نام دیا گیا۔
اب اسے تجربہ گاہ میں رکھ کر ایسے بیکٹیریا کا سامنا کرایا گیا جو اس سے قبل کولسٹائن اینٹی بایوٹک کو بری طرح ناکام بنارہے تھے۔ پھر چوہوں کو ایکس ڈی آر انفیکشن سے بیمار کیا گیا جس کے سامنے بھی ہماری آخری اینٹی بایوٹکس بے کار ہوتی ہے۔
حیرت انگیز طور پر سخت جان بیکٹیریا سے متاثر چوہے اس کمپاؤنڈ کے ایک ٹیکے سے ہی مکمل طور پر تندرست ہوگئے یعنی نیا مرکب انتہائی خطرناک بیکٹیریا کو بھی ناکام بنانے کے قابل ہوچکا تھا۔ اگلے مرحلے میں اس کی دوا بنا کر ایسے مریضوں پر آزمایا جائے گا جو مکمل طور پر اینٹی بایوٹکس سے مایوس ہوچکے ہیں۔
https://www.express.pk/story/2268608/9812/
امریکی انجینئروں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کرلیا ہے جو اسٹیپلر پن لگانے والی مشین جتنا مختصر ہے اور صرف پانچ سیکنڈ میں بلڈ پریشر معلوم کرسکتا ہے۔
یونیورسٹی آف مسوری کے ماہرین کی یہ ایجاد پروٹوٹائپ مرحلے پر ہے جسے اب تک 26 افراد پر آزمایا جاچکا ہے۔
آزمائشوں کے دوران اس آلے نے اوپر کا (سسٹولک) بلڈ پریشر 89 فیصد درستگی سے، جبکہ نیچے کا (ڈائیاسٹولک) بلڈ پریشر 63 فیصد درستگی سے معلوم کیا۔
اسے ایجاد کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر تیاری کی صورت میں یہ کارکردگی بہتر بنا کر تقریباً اتنی ہی کر دی جائے گی کہ جتنی مروجہ بلڈ پریشر میٹرز کی ہوتی ہے۔
اس آلے میں دو حساسیے (سینسرز) نصب ہیں جو فلیش لائٹ کی طرح تیز روشنی کے جھماکوں سے رگوں میں خون کی رفتار معلوم کرسکتے ہیں۔
بلڈ پریشر معلوم کرنے کےلیے اس آلے کو کسی کلپ کی طرح انگلی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔
اس کے دونوں سینسرز صرف چند ملی سیکنڈ (ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے) کے فرق سے انگلی میں دو الگ الگ مقامات پر خون کی رفتار معلوم کرتے ہیں۔
آلے سے منسلک کمپیوٹر پروگرام، خون کی اسی رفتار کو استعمال کرتے ہوئے بلڈ پریشر معلوم کرلیتا ہے جس میں اسے صرف پانچ سیکنڈ لگتے ہیں۔
یہ طریقہ لگ بھگ وہی ہے جو جدید آکسی میٹرز (خون میں آکسیجن معلوم کرنے والے آلات) میں استعمال کیا جاتا ہے۔
ریسرچ جرنل ’’آئی ٹرپل ای ایکسپلور‘‘ کے تازہ شمارے میں یہ آلہ ایجاد کرنے والی ٹیم نے امید ظاہر کی ہے کہ رگوں میں خون کی رفتار معلوم کرکے بلڈ پریشر اور دھڑکنوں کی رفتار کے علاوہ خون میں آکسیجن کی مقدار، جسمانی درجہ حرارت اور سانس لینے کی شرح تک معلوم کی جاسکتی ہیں۔
یعنی مستقبل میں یہ آلہ بلڈ پریشر کے علاوہ بھی انسانی صحت کی کئی کیفیات فوری معلوم کرنے میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2267953/9812/
ٓبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر (اوسی ڈی) ایک دماغی نفسیاتی کیفیت ہے جس میں کوئی شخص ایک ہی عمل بار بار دہراتا ہے یا پھر ان دیکھے خوف کا شکار بھی ہوجاتا ہے۔ اب سائنسدانوں نے پہلی مرتبہ اس کیفیت کی دماغی برقی سرگرمی کے اصل مقام کا سراغ لگایا ہے۔
اس دریافت سے اوسی ڈی کی وجہ بننے والے برقی سگنلوں کو کمزور یا ان کی راہ بدل کر لاکھوں کروڑوں مریضوں کو سکون کی زندگی مل سکے گی جس کے لیے وہ مہنگی ادویہ کھانے پر مجبور ہیں۔ کئی ممالک میں ہر 100 میں سے دو افراد اوسی ڈی سے متاثر ہیں اور ان کی روزمرہ زندگی اجیرن ہوکررہ گئی ہے۔
براؤن یونیورسٹی میں بایو میڈیکل انجینیئر ڈیوڈ بورٹن اور ان کے ساتھیوں نے او سی ڈی کی شدید کیفیت میں مبتلا پانچ افراد کی دماغی سرگرمی کو تجربہ گاہ اور گھر میں نوٹ کیا۔ اس کے علاوہ چہرے کے تاثرات، جسمانی حرکات، دل کی دھڑکن اور دیگر کیفیات کو بھی نوٹ کیا۔
اس کے بعد رویے میں بدلاؤ اور دماغی (برقی) سرگرمی کے تعلق پرغورہوا۔ اگرچہ صرف چند لوگوں پر یہ تحقیق ہوئی ہے لیکن اس کے نتائج اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اس سے علاج کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ماہرین نے گھر اور تجربہ گاہ میں او سی ڈی کی وجہ بننے والے دماغی سگنلوں کی درست شناخت کی اور اس وقت جسمانی برتاؤ کا جائزہ بھی لیا۔
سائنسداں اس قابل ہوگئے ہیں کہ وہ دماغی برقی لہروں کو دیکھ کر بتاسکیں کہ اس وقت اوسی ڈی کی کتنی شدت ہے اور کس وقت مریض نارمل ہے۔ اس طرح دن اور رات میں دورے کا غلبہ اور شدت معلوم کی جاسکتی ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ اوسی ڈی ریکارڈ کرنے والا نظام دماغ کو سکون بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ آلات ڈی بی ایس یعنی ڈیپ برین سیمولیشن فراہم کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی او سی ڈی کو نوٹ کریں یہ اپنے طور پر برقی سرگرمی کی فائرنگ شروع کرکے اسے کم کرسکتے ہیں تاہم ڈی بی ایس کا عمل بہت کم فائدہ مند رہا ہے۔ کئی مریضوں میں تو اس کا کوئی فائدہ دیکھنے میں نہیں آیا۔
لیکن اب اوسی ڈی کا برقی پیٹرن معلوم کرکے ڈی بی ایس کو اس لحاظ سے تبدیل کیا جاسکتا ہے یعنی اوسی ڈی دیکھ کر بی ڈی ایس اپنے سگنل تبدیل کرے گا اور اس برقی عمل کو دبانے کا کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے سائنسدانوں نے ایڈاپٹو ڈی بی ایس کا نام دیا ہے۔
براؤن یونیورسٹی کے مطابق اوسی ڈی کی برقی سرگرمی کا سراغ پانے سے علاج کے نئے طریقے سامنے آئیں گے۔
https://www.express.pk/story/2267755/9812/
ڈیمنشیا اور الزائیمر کے عارضے اس وقت عالمی بحران بن چکے ہیں۔ اس ضمن میں ناک کی پھوار (نوزل اسپرے) کئی مراحل سے گزرتے ہوئے بہت جلد انسانوں پرآزمائی جائے گی۔
اوساکا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک اینٹی بایوٹک اور اینٹی آکسیڈنٹ پر مشتمل مائع بنایا ہے۔ پہلے تجربہ گاہ میں اس کی افادیت سامنے آئی، پھر چوہوں پر آزمائش ہوئی۔ اب بہت جلد اس کی آزمائش کی جائے گی۔ لیکن اس کا تحقیقی سفر بہت طویل ہے۔
2016ء میں رائفم پائسن نامی مشہور اینٹی بایوٹک دوا کے متعلق معلوم ہوا کہ یہ دماغی و عصبی زوال کی وجہ بننے والے زہریلے پروٹین کو روک سکتی ہے۔ تجربات کی رو سے ڈیمنشیا کے شروع میں اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے اور نیوروڈی جنریشن کو روک سکتا ہے لیکن کھانے کے صورت میں جگر متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔
پھر دوبرس بعد اینٹی بایوٹکس کو براہِ راست دماغ پر ڈال کر دیکھا گیا تو جگر متاثر نہیں ہوا۔ اس سے ماہرین کا حوصلہ بڑھا اور اس میں ایک قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ ریزوریٹرل شامل کیا گیا جو گہری چاکلیٹ میں پایا جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ رائفم پائسن اور ریزوریٹرل دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہےاور ڈیمنشیا کو سست کیا جاسکتا ہے۔
چوہوں پر آزمائش سے معلوم ہوا کہ ان کے دماغ میں ڈیمنشیا کو بڑھانے والے زہریلے پروٹین کو روکا جاسکتا ہے۔ یہی پروٹین جمع ہوکر الزائیمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس لیے ماہرین نے دو ادویہ کو ملا کر اسپرے کی شکل دی ہے۔ ناک میں ٹپکانے سے یہ براہِ راست دماغ تک پہنچتا ہے اور مضر پروٹین کو روکتا ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق اس کی 0.081 ملی گرام فی کلوگرام فی روزانہ کی مقدار بہت ہوگی جس کے کے سائیڈ افیکٹس نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ اب بہت جلد امریکا اور جاپان میں اسپرے کو انسانوں پر آزمایا جائے گا۔
https://www.express.pk/story/2267295/9812/
امریکی ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگاس میں کنزیومر الیکٹرونکس شو میں انسان نما روبوٹس کی نمائش کی گئی۔
اے ایف پی کے مطابق برطانیہ کی انجینئرڈ آرٹس کے ڈائریکٹر مورگین رو نے بتایا کہ امیکا نامی روبوٹس کو حتی الامکان انسانوں سے مماثل بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلموں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح روبوٹس انسانوں میں گھل مل گئے ہیں۔
’’مجھے یقین ہے کہ وہ وقت بھی آجائے گا،‘‘ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں 10 یا 20 سال لگ سکتے ہیں جب روبوٹس بغیر کسی خدشے کے ہمارے درمیان چلیں گے اور رہیں گے۔
یہ خبریں بھی پڑھیے:
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ’’امیکا‘‘ نامی روبوٹ کی کوئی ذات پات نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی مذہب یا سیاسی نظریہ ہے جبکہ اس کی کوئی جنس بھی نہیں۔ مورگین کے مطابق، روبوٹس کی ساخت اور تاثرات میں جان بوجھ کر کچھ خامیاں شامل کی گئی ہیں تاکہ وہ حقیقی انسانوں سے کچھ مختلف نظر آئیں؛ کیونکہ لوگ بالکل اپنی طرح کا کوئی مصنوعی وجود دیکھتے ہیں تو عجیب سا خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن جب اپنے سے الگ دیکھتے ہیں تو جھجک دور ہوجاتی ہے۔
https://www.express.pk/story/2268154/508/
چین کے مصنوعی سورج نے حرارت پیدا کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا، جان کر یقین نہ آئے
Jan 05, 2022 | 19:25:PM

بیجنگ(مانیٹرنگ ڈیسک) چین کے مصنوعی سورج نے حرارت پیدا کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ میل آن لائن کے مطابق گزشتہ دنوں اس نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر کو ایک بار پھر متحرک کیا گیا اور اب کی بار یہ مسلسل 17منٹ تک 12کروڑ 60لاکھ ڈگری فارن ہائیٹ حدت پیدا کرتا رہا۔ چینی سائنسدانوں کا تیار کردہ یہ مصنوعی سورج بھی توانائی پیدا کرنے کے لیے بالکل اسی طرح کے طریقہ کار پر چلتا ہے، جس طرح کا پراسیس اصلی سورج میں ہوتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق اس منصوعی سورج نے یہ نیاریکارڈ 30دسمبر کے روز قائم کیا۔اس تجربے کی کامیابی کا اعلان چائنیز اکیڈمی آف سائنسزانسٹیٹیوٹ آف پلازما فزکس کے محقق گونگ ژیان زو کی طرف سے کیا گیا ہے، جو چینی صوبے انہوئی کے دارالحکومت ہیفی میں کیے گئے اس تجربے کے انچارج تھے۔
گونگ ژیان زو کا کہنا تھا کہ”ہم 2021ءکی پہلی ششماہی میں 12کروڑ ڈگری سینٹی کریڈ پر اس ری ایکٹر کو 101سیکنڈز تک چلانے میں کامیاب ہوئے تھے، جو اس وقت کی سب سے بڑی کامیابی تھی تاہم اب ہم نے اسے 7کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ پر 1ہزار 56سیکنڈ تک چلانے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ ہم اس ری ایکٹر کو بتدریج 15کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت تک لیجانا چاہتے ہیں۔
https://dailypakistan.com.pk/05-Jan-2022/1386849?fbclid=IwAR1tQdTX-4eguQyEzUVTDYrSpfhn3RUH17LtaVHiWWHYK4q1vqIaNm6IOsk
سام سنگ نے ایک ہرفن مولا گول ڈبے نما پروجیکٹر بنایا ہے جسے کہیں بھی لے جاکر نصب کیا جاسکتا ہے۔ 180 درجے زاویے پر گھومنے والا پروجیکٹر دیوار پر 100 انچ طویل فلم دکھاسکتا ہے، سالگرہ مبارک کے پیغامات دکھاتا ہے اور رنگ برنگی ناچتی روشنیوں سے کمرہ بھرسکتا ہے۔
اسے فری اسٹائل پروجیکٹر کا نام دیا گیا ہے اور قیمت 899 ڈالر رکھی گئی ہے جس کے لیے پہلے سے آرڈر دیا جاسکتا ہے۔ بہت سارے فیچر کے ساتھ پروجیکٹر کا وزن صرف 830 گرام ہے اور یہ دیوار پر 30 سے 100 انچ کی ایچ ڈی تصاویر اور ویڈیو دکھاسکتا ہے۔ پروجیکٹر سے 550 لیومن کی روشنی خارج ہوتی ہے جو تاریک کمرے کو سینما بناتے ہوئے 1080 پکسل کی تصویر اور ویڈیو دکھاسکتی ہے۔
اسی پروجیکٹر میں 360 درجے پر آواز بکھیرنے والے پانچ واٹ کے اسپیکر بھی نصب ہے جو موسیقی بکھیرتے ہیں اور اوپر سے رنگین روشنائی گھر میں سالگرہ یا تقریب کو مزید خوشگوار بناتی ہیں۔ اس کا حساس مائیک آپ کی آواز کے تحت کام کرتا ہے۔
ویڈیو یا تصاویر کے لیے پروجیکٹر کو ایچ ڈی ایم آئی اور یو ایس بی جیک سے جوڑا جاسکتا ہے۔ اسے چلانے کے لیے سام سنگ ٹی وی کا سافٹ ویئر ہی استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اب نیٹ فلیکس اور یوٹیوب کی فلموں کو پروجیکٹر کی بدولت دیکھنا ممکن ہے۔
https://www.express.pk/story/2267626/508/
چین کے خلائی تحقیقی ادارے (سی این ایس اے) نے روس کے تعاون سے چاند پر ایک مشترکہ خلائی اڈہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔
یہ خلائی اڈہ جسے ’انٹرنیشنل لیونر ریسرچ اسٹیشن‘ (ILRS) بھی کہا جاتا ہے، چاند پر انسانی تاریخ کا پیچیدہ اور جدید ترین منصوبہ بھی ہوگا جسے 2027 تک چاند کے جنوبی قطب کے نزدیک تعمیر کیا جائے گا۔
بتاتے چلیں کہ اکیسویں صدی میں نئی خلائی دوڑ شروع ہونے کے بعد سے روس اور چین میں تعاون و اشتراک مسلسل بڑھ رہا ہے۔
چین پہلے ہی اعلان کرچکا ہے کہ وہ 2030 تک اپنے اوّلین خلانورد چاند پر اتار دے گا۔
خلائی اڈے کا منصوبہ اس سے الگ ہے کیونکہ یہ سارا کام خودکار روبوٹس کے ذریعے، تھری ڈی پرنٹنگ کی مدد سے لیا جائے گا۔
روس اور چین میں معاہدے کے تحت یہ دونوں ممالک طاقتور راکٹوں کے علاوہ ایسی تعمیرات پر بھی کام کریں گے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعوں کا بہ آسانی سامنا کرنے کے قابل ہوں۔
اس حوالے سے چین کی خلائی پروازوں کا آغاز 2024 سے متوقع ہے جن کے ذریعے روبوٹ، روورز (پہیوں والی گاڑیاں) اور تھری ڈی پرنٹرز جیسے آلات چاند پر پہنچائے جائیں گے جو وہاں موجود مٹی اور پتھر استعمال کرتے ہوئے، اڈے کی تعمیر شروع کردیں گے۔
قبل ازیں اس منصوبے کو 2035 تک مکمل ہونا تھا لیکن چین اور روس میں اشتراک سے اب اس کے بہت جلد پایہ تکمیل کو پہنچنے کی امید بڑھ گئی ہے۔
امریکی حلقوں میں روس اور چین کا یہ بڑھتا ہوا تعاون تشویش کی نگاہ سے دیکھا جارہا ہے کیونکہ یہ چاند پر پہلا بڑا عالمی منصوبہ ہوگا جس میں امریکا کی کوئی شراکت نہیں۔ اس سے خلائی تحقیق کے میدان میں امریکا کی مسلمہ اہمیت متاثرہ ہونے کا خدشہ ہے۔
یہی نہیں بلکہ چاند پر اڈّے تعمیر کرنے کےلیے موجودہ ٹیکنالوجیز کو بھی خاصی ترقی دینا ہوگی جو آنے والے برسوں میں امریکی سالمیت کےلیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔
https://www.express.pk/story/2267180/508/
نت نئی اختراع کی دوڑ میں سام سنگ نے نہ صرف کامیاب فولڈنگ فون پیش کرکے اپنی اہمیت منوائی اور اب وہ ٹی وی اور مانیٹرسازی کی دوڑ میں بھی شامل ہوگیا ہے۔ سال کے آغاز پر سام سنگ نے جو دو بڑی خبریں دی ہیں ان میں سے ایک 32 انچ کا ایم 8 نامی مانیٹر ہے جو کسی بھی کمپیوٹر سے باآسانی جڑسکتا ہے۔ دوسری خبر بلاک چین اور این ایف ٹی ٹیلی ویژن کی ہے۔
ایم ایٹ نامی مانیٹر جو “انٹرنیٹ آف تھنگس” (آئی او ٹی) کے خواص رکھے گا اور فورکے ریزولوشن دکھاتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ جو گھریلو اشیا اس کی اہل ہوں گی، وہ اسکرین سے کنٹرول ہوجائیں گی جن میں ایئرکنڈیشن، ٹی وی، روشنیاں اور اس سے جڑے تمام ضروری آلات ہوسکتےہیں۔ یعنی اب گھریلو اشیا مانیٹر سے قابو کی جاسکیں گی۔
اکثرمانیٹر پر ویب کیم نہیں ہوتا لیکن ایم ایٹ میں بلند معیار کا مقناطیسی کیمرہ لگایا گیا ہے جو زوم میٹنگ اور ویڈیو چیٹ میں استعمال ہوسکے گا۔ اس کے علاوہ ایم ایٹ مانیٹر ورک اسپیس اور گیمنگ کے لیے بطورِ خاص ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے ایک گیم کلاؤڈ سے جڑسکے گا۔
این ایف ٹی اور بلاک چین ٹی وی
سام سنگ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے نئے ٹی وی سیٹ پر این ایف ٹی سپورٹ موجود ہے اور وہ گھر بیٹھے این ایف ٹی مارکیٹ کا جائزہ لے سکیں گے اور اس کی خریدوفروخت میں بھی شامل ہوسکیں گے۔ یوں ایک ہی جگہ این ایف ٹی کی ساری معلومات حاصل کرنا ممکن ہوگا۔
نان فنج ایبل ٹوکن (این ایف ٹی) ایسی ڈجیٹل تصاویر، دستاویز،آڈیو، ویڈیو اور خاکوں کو کہا جاتا ہے جو تاریخی اہمیت رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے انہیں کمپیوٹر پر ہی بنایا جاتا ہے۔ گزشتہ برس این ایف ٹی کی خریدوفروخت میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ این ایف ٹی بلاک چین پر بنائی جاتی ہیں اور انہیں کرپٹوکرنسی میں خریدا جاتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2266896/508/
تقریباً ہر گھر میں استعمال ہونے والی اس عام مشین کا طریقہ کار ایک انجینئر پرسی اسپینسر نے حادثاتی طور پر دریافت کیا تھا۔
ریتھیون کارپوریشن نامی کمپنی میں پرسی بحیثیت انجینئر کے طور پر ملازم تھے۔ ایک دن وہ میگنیٹرون نامی ریڈار ڈیوائس پر کام کررہے تھے کہ ان کی جیب میں رکھی چاکلیٹ پگھلنا شروع ہوگئی۔ وہ سمجھ گئے کہ ایسا مائیکرو ویوز شعاعوں کی وجہ سے ہورہا ہے جو ڈیوائس سے خارج ہورہی ہیں۔
پرسی نے پھر مائکرو ویو میں میں رکھی گئی دنیا کی پہلی غذا پاپ کارن پر تجربہ کیا اور وہ بھی کامیاب رہا۔ نتائج کو سامنے رکھ کر مائیکرو ویوز شعاعوں کو ایک محفوظ ڈبے میں بند کرنے کا سوچا گیا۔
8 آکتوبر 1945 میں پرسی نے سند ایجاد کیلئے درخواست دائر کردی۔ جس کے بعد پرسی نے پہلے مائکروویو اوون کی نمائش کی جسے ریڈار رینج نام دیا گیا اور جس کا سائز ایک ریفرجیریٹر کے برابر تھا۔
تاہم ایجاد کے بعد دہائیوں تک اسے عام گھریلو استعمال کیلئے نہیں پیش کیا گیا۔ 1967 میں جاکر پھر مائکرو ویو مارکیٹ میں فروخت کیلئے آیا۔
https://www.express.pk/story/2267244/508/
وہ سیارہ جس پر جانے سے انسان بہت جلد بوڑھا اور آدم خور بن سکتا ہے، ماہرین کا ایسا دعویٰ کہ ایلون مسک کا خواب بھی دھرے کا دھرا رہ جائے
Jan 03, 2022 | 18:44:PM

سورس: Wikimedia Commons
نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) انسان کے مریخ پر جا بسنے کا خواب پورا ہونے کے قریب ہے اور سپیس ایکس کے بانی ایلون مسک اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں انسانوں کو مریخ پر منتقل کرنے میں مزید زیادہ سے زیادہ 10سال کا عرصہ لگے گا۔ تاہم اب ماہرین نے مریخ پر جانے کے کچھ ایسے خوفناک نقصانات بتا دیئے ہیں کہ چاہ کر بھی کوئی مریخ پر نہیں جانا چاہے گا۔ ڈیلی سٹار کے مطابق ان ماہرین کا کہنا ہے کہ مریخ پر ممکنہ طور پر انسان بہت جلد بوڑھے ہو جایا کریں گے اور اس سیارے پر جا کر انسانوں کے آدم خور بن جانے کا بھی امکان ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین پر انسانوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، مریخ پر یہ چیلنجز کئی گنا سنگین نوعیت کے ہوں گے۔ ان میں خوراک کا مسئلہ سب سے بڑا ہو گا۔ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے زمین سے اشیائے خورونوش کی فراہمی تعطل کا شکار ہوئی تو مریخ پر موجود انسانوں کے پاس ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے گا۔ ایڈنبرا یونیورسٹی کے ایسٹروبائیولوجی کے پروفیسر چارلس کوکیل کا کہنا ہے کہ ”بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود مریخ پر انسانی زندگی کو استحکام ملنا انتہائی مشکل ہے۔ انسانوں کو مریخ پر منتقل کرنے سے پہلے وہاں زراعت اور دیگر نظام ہائے زندگی کو مستحکم کرنا ہو گا۔ ان کے بغیر انسانوں کو وہاں منتقل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔“
میو کلینک کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مریخ پر لوگ زمین کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوں گے۔ سائنسدانوں نے ’Cell Senescence‘ نامی ایک پراسیس کو اس کی وجہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مریخ پر انسانوں میں یہ پراسیس ممکنہ طور پر تیز تر ہو جائے گا اور وہ جلد بوڑھے ہو جائیں گے۔ میو کلینک کے ڈاکٹر جیمز کرکلینڈ کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے آئندہ ماہ باقاعدہ تحقیق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جس کے نتائج میں حتمی طور پرمعلوم ہو سکے گا کہ مریخ پر لوگ زمین کی نسبت کس قدر جلد بوڑھے ہوں گے۔
https://dailypakistan.com.pk/03-Jan-2022/1385946?fbclid=IwAR2nuj5ksi3X97VBne_6LtjBDRhh26c-seaPn5DoNcU4roHBVQdgBC6Q0CY
برطانوی اور امریکی سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر یہ خیال پیش کیا ہے کہ نئے پودے اور درخت لگانے کے علاوہ اگر جنگلوں کو بھی وقفے وقفے سے منظم انداز میں آگ لگائی جاتی رہے تو اس سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کم کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔
آن لائن ریسرچ جرنل ’’نیچر جیو سائنس‘‘ کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلوں میں قدرتی طور پر لگنے والی آگ اکثر انسان کے قابو سے باہر ہوجاتی ہے جس سے بڑے پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں خارج ہوتی ہے۔
عموماً یہ آگ اسی وقت بجھتی ہے جب جنگل پوری طرح سے جل کر بھسم ہوچکے ہوتے ہیں؛ اور نتیجتاً فضائی آلودگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ مٹی کی زرخیزی بھی کم ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے آئندہ وہاں پر نئے پودوں اور درختوں کا اُگنا بھی خاصا مشکل ہوجاتا ہے۔
اس کے برعکس، اگر جنگلوں میں درختوں کو انسانی نگرانی میں ایک مخصوص وقت تک جلانے کے بعد بجھا دیا جائے تو یہ عمل ماحول کےلیے مفید ثابت ہوسکتا ہے۔
اپنی تحقیق میں ماہرین نے کہا کہ جنگلوں میں مصنوعی یعنی ’منضبط آتش زدگی‘ (کنٹرولڈ فائر) کا درجہ حرارت قدرتی آتش زدگی کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔
مصنوعی آتش زدگی کے بعد بڑی تعداد میں چارکول (نامیاتی کوئلے) کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنتے ہیں جن کے درمیان میں کاربن سے بھرپور مواد موجود ہوتا ہے۔
کاربن سمیت، اپنے اسی نامیاتی مادّے کی بدولت یہ مٹی میں پائے جانے والے مفید جرثوموں اور پھپھوندیوں کو تقویت پہنچاتا ہے۔
ماہرین کے مطابق، منضبط آتش زدگی سے بعض علاقوں میں گھاس کی نشوونما بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی جڑوں میں زیادہ نامیاتی مادّہ ہوتا ہے۔
گھاس کی جڑوں میں زیادہ نامیاتی مادّے کی صورت میں کاربن کی بھی زیادہ مقدار زیرِ زمین محفوظ ہوجاتی ہے جو بصورتِ دیگر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شکل میں خارج ہو کر فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔
غرض یہ کہ جنگلات میں چھوٹے پیمانے پر مصنوعی و منضبط آتش زدگی سے مٹی کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہوئے ماحولیاتی نقصانات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2266707/508/
سال 2021ء کا دور اگرچہ کووڈ 19 اور سیاسی افراتفری کی نذر ہوگیا لیکن بالخصوص برطانوی ماہرین نے لاک ڈاؤن میں بھی تحقیق کی اور 550 نئی انواع اور جان دار دریافت کیے۔ اسی ضمن میں امریکی ماہرین نے 70 سے زائد نئے پودوں اور جانوروں کی نئی انواع کا اعلان بھی کیا۔
کیلی فورنیا اکادمی برائے سائنس کے ماہرین نے خوبصورت تارہ مچھلی، نیلی نشانات والی گٹار فِش اور پائپ ہارس سمیت 70 نئی انواع کا اعلان کیا۔ اکادمی کے سربراہ شینن بینٹ کے مطابق ان دریافتوں سے حیاتیاتی درخت یا ٹری آف لائف کو مزید سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ان کے مطابق نئی دریافتیں مڈغاسکر، میکسیکو اور ایسٹر جزائر سے ہوئی ہیں۔

ان جان داروں میں 14 بھنورے، 12 اقسام کی سی سلگ، نو اقسام کی چیونٹیاں، مچھلیوں کی چھ اقسام، چھ طرح کے بچھو، پانچ اقسام کے پھول دار پودے، چارمختلف شارک، تین مکڑیاں، ایک قسم کی سمندری گھاس اور دیگر جان دار شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ایک خوبصورت تارہ مچھلی بھی دریافت ہوئی ہے۔

دوسری جانب برطانوی ماہرین نے کووڈ لاک ڈاؤن میں اپنے اس خزانے کو کھنگالا جن میں لاتعداد رکازات (فاسلز) موجود تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے دو نئے گوشت خور ڈائنوسار دریافت کیے جن میں سے ایک کو چیف ڈریگن کا نام دیا گیا ہے۔
میوزیم سے تعلق رکھنے والی سائنسداں سوسانا مینڈمنٹ نے کہا ہے کہ کووڈ 19 کی پابندیوں کی وجہ سے باہرنکلنا ممکن نہ تھا لیکن میوزیم کے اسٹاف نے دنیا کے ڈیٹا اور پہلے سے موجود نمونوں پر غور کیا۔

لندن میں واقع نیچرل ہسٹری میوزیم کے ماہرین نے اس تحقیق کو لاک ڈاؤن منصوبے کا نام بھی دیا ہے۔ اس پورے مرحلے میں نئے پودوں، جانوروں، حشرات اور ناپید ہوجانے والے کئی جاندار بھی سامنے آئے ہیں۔ مجموعی طور پر برطانوی ماہرین نے 550 سے زائد نئی انواع کا انکشاف کیا ہے۔
https://www.express.pk/story/2266514/508/
ڈیزل انجن پیٹرول انجن کے مقابلے میں زیادہ موثر اور بہتر کارکردگی کا حامل ہوتا ہے۔ ڈیزل انجن حرارت کی مقدار کی مناسبت سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔
ڈیزل انجن جرمن انجینئر رڈولف ڈیزل نے 1897 میں ایجاد کیا تھا۔ اسے تیار کرنا بھی پیٹرول انجن کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ پیٹرول انجن کو اسپارک اگنیشن انجن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انجن کو چالو کرنے کیلئے اسپارک پلگ اور فیول کو جلانا پڑتا ہے جبکہ ڈیزل انجن کا انحصار منقبض ہوا (compressed air) پر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اسپارک پلگ یا فیول کو جلانے کی جھنجٹ نہیں ہوتی اور انجن صرف حرارت کے پیدا ہوتے ہیں اسٹارٹ ہوجاتا ہے۔
دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں انجنوں کی تیاری کا طریقہ کار تقریباً ایک ہی ہوتا ہے لیکن بنیادی فرق انجن میں فیول کو تعارف کرانے اور پھر اس کے توانائی میں تبدیل ہونے کا ہے۔
آسان طریقہ کار کے باوجود ڈیزل انجن پیٹرول انجن سے مہنگا کیوں ہوتا میں؟، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انجن میں ہوا کو ہائی پریشر میں رکھ کر قید کیا جاتا ہے لہٰذا اس کا انجن بھی اُسی حساب سے زیادہ طاقتور اور بھاری ہوتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2266008/508/
تیل پانی میں نہیں گھُلتا اور نہ پانی تیل میں ضم ہوسکتا ہے، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں اور اس کا مشاہدہ گھروں میں کرتے ہونگے لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟، اس بارے میں کبھی غور نہیں کرتے۔
تیل اور پانی کا ملاپ اس وجہ سے ناممکن ہے کیونکہ ان کے مالیکیولز (molecules) کی ساخت اور خصوصیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تیل کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ پانی کے مالیکیولز کے مقابلے میں کافی بڑے اور زیادہ جوہری ذرات (Atoms) پر مشتمل ہوتے ہیں۔
ہم دیگر اقسام کے مائع (liquids) کو جو آپس میں ملتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکنیکی اعتبار سے ان کی خصوصیات ایک جیسی ہیں مثلاً دودھ اور پانی۔
ایک اور مشاہدہ جو ہم نے کیا ہوگا وہ یہ کہ جب تیل اور پانی کو ملایا جاتا ہے تو تیل پانی کی سطح کے اوپر گول دائرے بنالیتا ہے۔ اصل میں تیل کے مالیکیلوز کی آپسی کشش زیادہ ہوتی ہے۔ مالیکیولز کم جگہ گھیرنے کی کوشش میں آپس میں اتنا مضبوطی سے جُڑتے ہیں کہ بجائے پانی کی پوری سطح کو ڈھانپنے کے چھوٹے بڑے گول دائروں کی شکل اختیار کرلیتے ہیں۔
https://www.express.pk/story/2265143/508/
پاکستان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے میدان میں ایک اہم سنگ میل عبور کرلیا ہے۔ گوگل کے اشتراک سے پاکستانی طلباء کی ڈیزائن کردہ مائیکروپروسیسر چپ تیار ہو کر پاکستان پہنچ گئی ہے۔
یہ مائیکروپروسیسر اوپن سورس ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے گزشتہ سال وسط میں ڈیزائن کرکے امریکا روانہ کیا گیا تھا جہاں سیمی کنڈکٹر انجینئرنگ اور فیبری کیشن فونڈری ”اسکائی واٹر ٹیکنالوجی“ نے اسے چپ کی شکل دی۔
اب یہ چپ مائیکروپروسیسر ڈیزائن کرنے والے، کراچی کے ”عثمان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی“ کو موصول ہوگئی ہے۔ عثمان انسٹی ٹیوٹ کے انڈر گریجویٹ طلباء کی اس کاوش کے ساتھ ہی پاکستان نے مائیکرو پروسیسرز اور چپ کی 500 ارب ڈالر کی عالمی مارکیٹ کی جانب ابتدائی لیکن بے حد اہم قدم اٹھالیا ہے۔
مائیکروپروسیسرز کی پاکستان میں ڈیزائننگ سے ڈیجیٹل سکیوریٹی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ اسمارٹ گھریلو برقی آلات، گاڑیوں، دفاعی مقاصد کےلیے پاکستان میں ڈیزائن کی جانے والے مائیکروپروسیسرز اور چپس ایک جانب پاکستان کے ڈیٹا کو تحفظ فراہم کریں گی، وہیں ان چپس کی درآمد پر اٹھنے والے زرمبادلہ کی بھی بچت ہوگی۔
سسٹم آن چپ مائیکرو پروسیسرز، سوئٹزرلینڈ میں واقع عالمی ادارے کے تشکیل کردہ اوپن سروس انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکٹ ’’وی رِسک‘‘ (V-RISC) پر مشتمل ہے۔
مائیکرو پروسیسر عثمان انسٹی ٹیوٹ میں واقع پاکستان کی پہلی مائیکرو الیکٹرونکس ریسرچ لیبارٹری میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجیز پر ہونے والی تحقیق کا نتیجہ ہے جو ڈاکٹر علی احمد انصاری کی نگرانی میں انجام دی گئی۔
ڈاکٹر انصاری کے مطابق، مائیکروپروسیسرز ڈیزائن کرکے پاکستانی طلباء نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کو ثابت کردیا ہے اور وہ مائیکروپروسیسرز کی 500 ارب ڈالر حجم والی عالمی صنعت سے خطیر حصہ بھی حاصل کرسکتے ہیں۔
پاکستان میں مائیکروپروسیسرز کی پیداوار کےلیے بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، تاہم بین الاقوامی فیبری کیشن کمپنیوں کے اشتراک سے پاکستان اپنے مائیکروپروسیسرز تیار کرواسکتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2265114/508/
چینی ماہرین نے مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ایک ایسا نظام بنا لیا ہے جو بالکل کسی سرکاری وکیل کی طرح کام کرتے ہوئے ملزم کے خلاف ریاست کی طرف سے بھرپور وکالت کرتا ہے۔
شنگھائی کے محکمہ قانون میں ابتدائی آزمائشوں کے دوران اس نظام نے 97 فیصد درستگی کا مظاہرہ کیا، جسے اطمینان بخش قرار دیا جارہا ہے۔
تفتیش کی غرض سے اس نظام کو کسی فوجداری (کریمنل) مقدمے کی تمام تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں جنہیں کھنگالنے کے بعد یہ ’’سب سے زیادہ مشکوک ملزم‘‘ کی نشاندہی کرتا ہے۔
’’ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ‘‘ کے مطابق یہ خودکار نظام فراڈ، جوئے، جان بوجھ کر حملے، چوری، کارِ سرکار میں مداخلت اور خطرناک ڈرائیونگ سمیت آٹھ اقسام کے جرائم شناخت کرسکتا ہے جبکہ اسی حساب سے مشکوک ترین ملزم اور جرم کی نوعیت کی نشاندہی بھی کرسکتا ہے۔
اس بارے میں چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ سرکاری وکیل کی جگہ نہیں لے گا، البتہ مقدمات کی کارروائی میں ان کی مدد اور رہنمائی ضرور کرے گا۔
واضح رہے کہ چین میں سرکاری وکلاء پہلے ہی مختلف مقدمات میں ’’سسٹم 206‘‘ کے نام سے شہرت رکھنے والے ایک سافٹ ویئر سے مدد لے رہے ہیں جو مصنوعی ذہانت سے لیس ہے۔
نیا نظام اسی سافٹ ویئر میں بہتری اور اضافہ جات کرکے تیار کیا گیا ہے جو کسی بھی کیس کی باریک ترین تفصیلات (پولیس رپورٹس، گواہوں کے بیانات اور شہادتوں وغیرہ) کو بڑی تیزی اور احتیاط سے ’’پڑھ‘‘ کر ان میں سے متعلقہ نکات منتخب کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ ملزم کو مجرم قرار دیا جائے یا نہیں۔
اس خبر کی اشاعت پر مصنوعی ذہانت کی اخلاقیات سے وابستہ ماہرین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ اگر اس نظام نے غلطی سے کسی بے گناہ کو مجرم قرار دے دیا تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟
سرِدست یہ نظام آزمائشی مرحلے پر ہے جسے کئی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہی بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے گا۔ ایسا کب ہوگا؟ فی الحال اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔
https://www.express.pk/story/2265076/508/
ایک امریکی ڈیزائنر ’جو ڈوسے‘ نے ہوا سے بجلی بنانے والی دیوار ایجاد کرلی ہے جو بہت کم جگہ گھیرنے کے باوجود پورے سال میں تقریباً دس ہزار یونٹ جتنی بجلی بنا سکتی ہے۔
اس دیوار کو ’وِنڈ ٹربائن وال‘ کا نام دیا گیا ہے جس کے مختلف خوبصورت ڈیزائن بھی تیار کیے جاچکے ہیں۔
ایسی ہر دیوار میں درجنوں ہلکی پھلکی پنکھڑیاں نصب ہیں جو تھوڑی سی ہوا چلنے پر بھی گھومنے لگتی ہیں جس سے بجلی بننے لگتی ہے۔
اس ’وِنڈ ٹربائن وال‘ کی چوڑائی 24 فٹ جبکہ اونچائی 8 فٹ ہے، یعنی یہ اوسط رقبے والے ایک مکان کی چھت پر آسانی سے نصب کی جاسکتی ہے۔
اسے بڑے مکان کی راہداری میں بھی رکھا جاسکتا ہے جبکہ یہ دفتروں کی زینت بھی بن سکتی ہے۔

اس دیوار سے نہ صرف بجلی کا بِل کم کرنے میں مدد ملے گی بلکہ یہ گھروں اور دفاتر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گی۔
واضح رہے کہ کوئلے، تیل اور گیس کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے قدرتی ذخائر اور مسلسل بڑھتی آلودگی کی وجہ سے آج دنیا بھر میں توانائی کے ایسے متبادل ذرائع پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے جو ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات بھی بخوبی پوری کرسکیں۔

اسی بناء پر ہوا سے بجلی کی پیداوار یعنی ’وِنڈ پاور‘ کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے کیونکہ یہ نسبتاً سادہ اور آسان بھی ہے۔
اس وقت دنیا بھر میں ہوا کی طاقت سے 743 گیگا واٹ بجلی بنائی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ 2030 تک دنیا بھر میں بجلی کی کم از کم 20 فیصد ضرورت ہوا کی طاقت ہی سے پوری کی جارہی ہوگی
https://www.express.pk/story/2264677/508/
خلا میں بھیجے جانے والے جہازوں میں نہ تو فیول بھرنے کی اتنی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی خلا میں پیٹرول پمپ کی طرح کوئی اسٹیشن، پھر یہ خلائی جہاز، سیٹلائٹس یا ٹیلی اسکوپ وغیرہ طویل عرصے تک فعال رہنے کیلئے برقی توانائی کہاں سے حاصل کرتی ہیں؟
جواب اس کا سیدھا سادا ہے، سولر پینل۔ جی ہاں! خلائی جہازوں یا دیگر خلائی آپریشن میں استعمال ہونے والی مشینوں میں سولر پینلز نصب ہوتے ہیں۔ جو سورج کی شعاعوں کو بجلی میں تبدیل کرتے ہیں بالکل ہمارے گھروں میں لگے سولر پینلز کی طرح۔
تاہم گھر کے سولر پینل اور خلا میں سولر پینل میں فرق یہ ہے کہ وہاں سورج ہمیشہ دمکتا رہتا ہے بنسبت دنیا میں کیونکہ رات کے وقت ہم بیٹریوں پر گزارا کررہے ہوتے ہیں۔
لیکن کچھ مشینوں کو دور دراز سیاروں کے معائنے کیلئے بھی بھیجا جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی بہت کم ہوتی ہے۔ ایسی مشینوں میں پھر سولر پینل کے بجائے نیوکلیئر پاور پلانٹس موجود ہوتے ہیں جو دیر پا نیوکلیئر توانائی کو بجلی میں تبدیل کرنے کے حامل ہوتے ہیں۔
https://www.express.pk/story/2264788/508/
https://e.dunya.com.pk/detail.php?date=2021-12-30&edition=KCH&id=5898561_79928107
دفاعی تحقیق کے امریکی ادارے ’ڈارپا‘ کی نگرانی میں سمندری گہرائی میں خودکار انداز سے سفر کرنے والے ڈرونز کا منصوبہ ’مینٹا رے ڈرون پروگرام‘ اپنے دوسرے اور نئے مرحلے میں داخل ہوگیا ہے۔
اس زیرِ آب ڈرون کے بڑے اور پھیلے ہوئے پر ہوں گے جن کی وجہ سے یہ ’مینٹا رے‘ مچھلی کی طرح دکھائی دے گا۔
اس بارے میں خبروں سے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ ’مینٹا رے انڈر واٹر ڈرونز‘ کی جسامت بہت بڑی ہوگی لیکن اب تک ان کی حتمی جسامت کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔

نئے مرحلے کےلیے دو امریکی دفاعی اداروں، نارتھروپ گرومین اور مارٹن ڈیفنس گروپ کو منتخب کیا گیا ہے جو اپنے اپنے طور پر اصل جسامت والے مینٹا رے ڈرونز تیار کریں گے۔
ان میں سے جو ڈیزائن بھی امریکی محکمہ دفاع (پنٹاگون) کو زیادہ مناسب لگے گا، اسی کو آخری اور پیداواری مرحلے کےلیے منتخب کیا جائے گا۔
’ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی‘ (ڈارپا) کے مطابق، ایسے کسی بھی ڈرون کو سمندر میں لمبے فاصلے تک پہنچنے کے علاوہ نمکین سمندری پانی کے اندر طویل مدت تک محفوظ اور کارآمد حالت میں رہنے کے قابل بھی ہونا چاہیے۔
علاوہ ازیں، ڈارپا کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اس ڈرون کو مرمت اور دیکھ بھال کےلیے انسانی مداخلت کی بھی کم سے کم ضرورت پڑے جبکہ اس کی بیٹریاں بھی طاقتور ہوں جو سمندری پانی کے بہاؤ سے خود کو دوبارہ چارج بھی کرسکیں۔

ان تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ ’مینٹا رے‘ ڈرونز کا حساس آلات سے لیس ہونا بھی لازمی ہے تاکہ وہ سمندر کی گہرائی میں رہتے ہوئے دور دراز مقامات پر نظر رکھ سکیں اور امریکی افواج کو دشمن آبدوزوں اور بحری جہازوں کی نقل و حرکت سے بروقت آگاہ کرتے رہیں۔
اس منصوبے کی تکمیل کے ساتھ ہی امریکی فوج کو خلا، فضا اور زمین کے علاوہ سمندر کی گہرائی میں بھی جاسوسی کی صلاحیت حاصل ہوجائے گی۔
https://www.express.pk/story/2263901/508/
سائنس دانوں نے سمندر کے اوپر منڈلانے والے ایک بالکل نئے قسم کے طوفان کو ’فضائی جھیل‘ کا نام دیا ہے جسے پہلے دیکھا تو گیا تھا لیکن سمجھا نہیں گیا تھا۔
یہ ہوائی بگولوں کی وجہ سے بنتا ہے جس کی رفتار بہت مدھم ہوتی ہے اور پانی کے وسیع ذخائرپر مشتمل یہ نظام بارش برسانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے مغربی بحرِہند سے افریقی سمندروں تک جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔
سمندری ماحول کے عین اوپر اس سے قبل تنگ اور طویل فضائی کیفیات نوٹ کی گئیں جن میں پانی کی وسیع مقدار بھری ہوتی ہے جنہیں سائنسدانوں نے فضائی دریا کا نام دیا تھا۔ عین نمی سے بھرپور یہ گول دائرے ہوتی ہیں جنہیں فضائی جھیل یا ایٹماسفیئرک لیک کہا گیا ہے۔
ان کی دلچسپ بات یہ ہے کہ فضائی جھیل پورے فضائی موسم سے الگ تھلگ کٹ کر رہتی ہے۔ اس کی تفصیلات امریکن جیوفزیکل یونین کی موسمِ خزاں کی حالیہ کانفرنس میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔
تحقیق کے مطابق نمی سے بھرے چھوٹے چھوٹے نظاموں کو افریقی ساحلوں تک جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جہاں یہ نیم بجنر علاقوں اور ساحلوں پر بارش برسارہے ہیں۔

ماہرین نے مسلسل 5 سال تک فضائی جھیلوں پر غور کیا ہے جو سست روی سے آگے بڑھتے ہیں اور طویل ترین طوفانی جھیل 27 روز تک برقرار رہی تھی۔
پانچ سال میں مجموعی طور پر 17 جھیلوں کو دریافت کیا گیا ہے جو خطِ استوا کے اردگرد دس ڈگری پر دکھائی دی ہیں۔ خیال ہے کہ دیگر علاقوں میں یہ فضائی کیفیات پیدا ہوسکتی ہیں جہاں وہ بڑے سائیکلون کی شکل اختیار کرلیتی ہیں۔
سائنسدانوں نے فضائی جھیلوں کی تشکیل اور دیگر موسمیاتی کیفیات سے الگ ہونے کے سوالات پر بہت غور کیا ہے۔ پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ شاید اندر کی جانب تیز ہوا سے یہ سب کچھ بنتا ہے اور دوم مجموعی فضائی اور موسمیاتی کیفیات اسے جنم دے رہی ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق کلائمٹ چینج کا پہلو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا اور وہ اندرونی قوت کے تحت ایک جگہ سے دوسرے ملک جاتے رہتے ہیں۔
لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس سے مشرقی افریقا کے ساحلی علاقوں میں بارشیں ہونے لگی ہیں لیکن بارشوں کی یہ مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ ایک مصنوعی جھیل پورے سال ایک کلومیٹر وسیع سوئمنگ پول کو چند سینٹی میٹر تک ہی بھر سکتی ہے۔
https://www.express.pk/story/2263704/508/
کولون جرمنی:اگرچہ ماہرین ایک عرصے سے اس پر غور کررہے ہیں لیکن 2018 میں پہلی مرتبہ انکشاف ہوا کہ دماغ میں ہونے والی عجیب و غریب تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جس سے دماغی ٹوٹ پھوٹ اور اس سے ہونے والی دماغی موت کو پلٹانا ناممکن ہوجاتا ہے۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ ہے کہ دماغ میں برقی کیمیائی (الیکٹروکیمیکل) جھکڑ چلتا ہے جس سے موت واقع ہوجاتی ہے۔
لیکن خبر یہ ہے کہ اب چار سال بعد سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ دماغی موت کی وجہ بننے والی سونامی کو روکا بھی جاسکتا ہے۔ لیکن یہ عمل آسان نہ تھا اور اس کا مشاہدہ سب سے پہلے جانوروں پر کیا گیا تھا۔
جانوروں میں موت سےقبل صرف 20 سے 40 سیکنڈ پہلے دماغ کی آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے۔ اب یہاں دماغ ’توانائی محفوظ کرنے والی حالت‘ یا انرجی سیونگ موڈ میں چلاجاتا ہے۔ اس کے اندر برقی سرگرمی ماند پڑجاتی ہے اور عصبیوں (نیورون) کا باہمی رابطہ منقطع ہوجاتا ہے۔
چند منٹ بعد دماغی خلیات کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ اب اس موقع پر برق کیمیائی (الیکٹروکیمیکل) توانائی کی ایک لہر پورے دماغ میں دوڑتی ہے جسے سائنسدانوں نے ’دماغی سونامی‘ قرار دیا ہے جو قشر(کارٹیکس) تک جاتی ہے۔ اس کا ایک اور نامی ڈی پولرائزیشن بھی ہے۔ یہ کیفیت دماغ کی موت ہوتی ہے جسے کسی بھی صورت ٹھیک نہیں کیا جاسکتا۔
اب جرمنی کے پروفیسر ینس درائیر نے نو مریضوں کو دیکھا جو شدید دماغی چوٹ کےباعث ہسپتال میں داخل تھے۔ ان کے مطابق دماغ میں آکسیجن کا بہاؤ رک جانے کے بعد بھی اسے بحال کرکے دماغ کو زندہ کیا جاسکتا ہے۔
’ دماغی بہاؤ تھم جانے کے بعد دماغی خلیات میں جمع برق کیمیائی توانائی ایکدم خارج ہوتی ہے۔ اس کے بعد زہریلےمرکبات جمع ہوجاتے ہیں اور دماغ مرتا ہے جس کے بعد خود انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے،‘ پوفیسر ینس نے کہا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس عمل کو لوٹایا جاسکتا ہے۔
ایک نئی ٹیکنالوجی ’سب ڈیورل الیکٹروڈ اسٹرپس اینڈ انٹراپیرنکائمل الیکٹروڈ ایریز‘ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت مریض کے دماغ میں ڈی پولرائزیشن پر نظر رکھی جاسکتی ہے۔ اس تدبیر سے دماغ میں آکسیجن کو بحال کرکے سونامی کو ٹالا جاسکتا ہے۔
دلچسپ بعد یہ ہے کہ پورے دماغ میں خلوی نقصانات کے بغیر ہی تباہ کن سونامی کو روکا جاسکتا ہے جو آکسیجن کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔
اس اہم دریافت سے دماغ میں خون کی کمی اور فالج کے مریضوں کو بھی بحال کرنے میں اہم مدد مل سکے گی اور ایک دن یہ ایجاد قیمتی انسانی جانوں کو بچانے میں معاون ہوگی۔ لیکن اس سے قبل نئی تکنیک پر تفصیلی تحقیق کی ضرورت ہوگی۔
https://www.express.pk/story/2264006/9812/
چینی کمپنی نے ایک انقلابی راہ اپناتے ہوئے ایسا پی سی آر ٹیسٹ اور اس کی مشین پر کام شروع کردیا ہے جس کی بدولت گھر بیٹھے ہر طرح کے پی سی آر ٹیسٹ خودکار طریقے سے انجام دینا ممکن ہوجائے گا۔
چینی کمپنی یواسٹار نے اس ضمن میں خاطرخواہ رقم بھی حاصل کرلی ہے اور اس کا پروٹوٹائپ بنایا ہے۔ یہ جدید ترین خودکار مشین ہے گھربیٹھے کئی امراض کی تشخیص اور طبی کاموں میں مدد دے سکے گی۔ یواسٹار نے پہلے ہی ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اس کے معیارت اور اسناد کی تصدیق کرلی ہے۔
یواسٹارطبی آلات سازی میں عالمی شہرت رکھتی ہے۔ اس کے کئی آلات دنیا کے 60 ممالک میں استعمال ہورہے ہیں اور صرف چین میں ہی 2000 ادارے اسے استعمال کررہے ہیں۔
یواسٹار کا پی سی آر پلیٹ فارم کووڈ 19 سمیت کئی وائرس اور جراثیم کے ڈی این اے پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جلد ہی یہ انفلوئنزا وائرس کی شناخت بھی کرسکتی ہے۔
https://www.express.pk/story/2263686/508/
خواتین کی انگلیوں کی لمبائی اور جسمانی طاقت میں دلچسپ تعلق سامنے آگیا
Dec 27, 2021 | 18:37:PM

ویانا(مانیٹرنگ ڈیسک) آسٹریا میں ماہرین نے نئی تحقیق میں خواتین کی انگلیوں کی لمبائی اور ان کی جسمانی طاقت کے درمیان ایک دلچسپ تعلق کا انکشاف کر دیا ہے۔ دی سن کے مطابق ماہرین نے بتایا ہے کہ جن خواتین کی انگوٹھی والی انگلی ان کی شہادت والی انگلی سے لمبی ہو وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔
سائنسی جریدے بائیولوجیکل سائنسز میں شائع ہونے والی اس تحقیقاتی رپورٹ میں ماہرین نے بتایا ہے کہ مردوں میں انگلیوں کی لمبائی اور جسمانی طاقت کے درمیان یہ تعلق قبل ازیں ایک تحقیق میں ثابت ہو چکا ہے اور اس تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ وہی قاعدہ خواتین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔
ماہرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ”انگلیوں کی لمبائی کا تعین مردانہ جنسی ہارمون ٹیسٹاسٹرون کے لیول کے تناسب سے ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس بچے(لڑکے یا لڑکی) کو ٹیسٹاسٹرون کی زیادہ مقدار ملتی ہے، اس میں جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ میں ٹیسٹاسٹرون زیادہ ملنے کی وجہ سے ہی ان کی انگوٹھی والی انگلی کی لمبائی شہادت کی انگلی سے زیادہ ہوتی ہے۔
https://dailypakistan.com.pk/27-Dec-2021/1383003?fbclid=IwAR1eVd32JvBy_aneOIjQaJK-PWpjygz_mtjEe9tD9KRf2JYDjdB4oFplG0o
مصر میں 3 ہزار سال پرانی مشہور حنوط شدہ امین ہوٹیپ اول کی ممی کو ڈیجیٹل طور پر ’کھول‘ دیا گیا، 1881 میں دریافت ہونے کے بعد اس کے ماسک کو ہٹایا نہیں گیا لیکن اب پہلی مرتبہ اس کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جارہا ہے۔
جدید ترین ڈیجیٹل تھری ڈی کے ذریعے محققین نے 1525 سے 1504 قبل مسیح تک حکمرانی کرنے والے فرعون کے لیے استعمال ہونے والی ممی بنانے کی نئی تکنیکوں کا پتا لگایا ہے۔
وزارت سیاحت اور نوادرات نے ایک بیان میں کہا کہ اس تحقیق کی قیادت قاہرہ یونیورسٹی میں ریڈیولوجی کے پروفیسر سحر سلیم اور معروف مصری ماہر زاہی حواس نے کی۔
انہوں نے بتایا کہ سحر سلیم اور زاہی حواس نے اعلی درجے کی ایکس رے ٹیکنالوجی، سی ٹی اسکیننگ کے ساتھ ایمن ہوٹیپ کی ممی کو ڈیجیٹل طور پر کھولنے کے لیے جدید کمپیوٹر سوفٹ ویئر پروگرامز کا استعمال کیا جس میں ممی کو چھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔
ان کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ بادشاہ امین ہوٹیپ اول کا چہرہ، ان کی عمر، صحت کی حالت، ممی کی منفرد ممی بنانے اور دوبارہ دفنانے کے بارے میں بہت سے رازوں انکشاف ہوئے ہیں۔
ماہرین کے مطابق امن ہوٹیپ پہلا فرعون تھا جسے بازوؤں سے ممی بنایا گیا تھا اور آخری فرعون تھا جس کا دماغ کھوپڑی سے نہیں نکالا گیا تھا۔
https://www.express.pk/story/2264329/1/
ماہرین کہتے رہے ہیں کہ خراب مسوڑھے عارضہ قلب اور دیگر بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں لیکن اب ایک نئی تحقیق دوسرے کنارے سے عین یہی کہانی سناتی ہے۔ اگر کسی طرح خون کے لوتھڑے بنانے والے پروٹین کو ختم کردیا جائے تو مسوڑھوں کی خرابی بھی دور ہوجاتی ہے۔
لیکن واضح رہے کہ ہم یہاں مسوڑھوں کی اس خطرناک کیفیت کا ذکر کررہے ہیں جسم میں وہ اپنی ہڈی سمیت گھلنے لگتے ہیں۔ اسے پیریڈونٹل کا مرض کہتے ہیں۔ اب میری لینڈ میں این آئی ایچ سے وابستہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈینٹل اینڈ کرینیئوفیشل ریسرچ (این آئی ڈی سی آر) کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ خون میں فائبرن نامی پروٹین بڑھنے سے جسم کا اپنا امنیاتی نظام مسوڑھوں پر حملہ کردیتا ہے۔ اب اس موقع پر فائبرین کو روک کے نہ صرف مسوڑھوں کے مرض بلکہ جوڑوں کی تکلیف اور دیگر امراض کو بھی دور کیا جاسکتا ہے۔
سائنسدانوں نے اس ضمن میں چوہوں پر تجربات کئے اور فائبرین پروٹین کو روکا گیا تو ان کے مسوڑھوں کا مرض بھی دور ہونے لگا۔
امریکا اور برطانیہ میں مسوڑھوں کی خرابی کا مرض بہت عام ہے جس کی شدید کیفیت میں دانت گرن لگتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فائبرین کی زیادتی سے خون گاڑھا ہونے لگتا ہے اور اس میں لوتھڑے بننے لگتے ہیں۔ اس طرح فائبرین جیسے پروٹین ساز نظام کو روک کر مسوڑھوں کی بیماری بلکہ خود خون میں لوتھڑے بننے کے عمل کو روکا جاسکتا ہے ۔ یوں فالج ، بلڈ پریشر اور امراضِ قلب سے بھی بچا جاسکتا ہے۔
https://www.express.pk/story/2263675/9812/











No comments:
Post a Comment